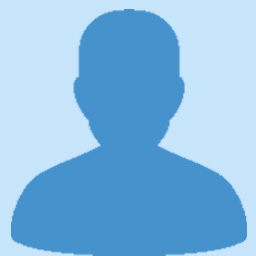ولا يبنيان إلّا ممّا يبنى منه أفعل التفضيل ، ويتوصّل في الممتنع بمثل ما أشَدَّ كما عرفت.
ولا يجوز التصريف فيه ولا التقديم ولا التأخير ولا الفصل. والمازني أجاز الفصل بالظرف نحو : ما أحْسَنَ الْيَوْمَ زَيْداً.
فصل : أفعال المدح والذمّ
ما وضع لإنشاء مدح أو ذمّ. أمّا المدح فله فعلان :
«نِعْمَ» ، وفاعله اسم معرّف باللام نحو : نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ ، أو مضاف إلى المعرّف باللام نحو : نِعْمَ غُلامُ الرَّجُلِ زَيْدٌ ، وقد يكون فاعله مضمراً يجب تمييزه بنكرة منصوبة نحو : نِعْمَ رَجُلاً زَيْدٌ ، أو بما نحو قوله تعالى : «فَنِعِمَّا هِيَ» (١) ، أي نِعْمَ ما هي ، وزيد يسمّى المخصوص بالمدح.
ومنها : «حَبَّذا» ، نحو : حَبَّذا رَجُلاً زَيْدٌ ، فَحَبّ فعل المدح وفاعله «ذا» والمخصوص زيدٌ ، ورجلاً تمييز ، ويجوز أن يقع قبل مخصوص حبّذا أو بعده تمييز نحو : حَبَّذا رَجُلاً زَيْدٌ ، وحَبَّذا زَيْدٌ رَجُلاً ، أو حال نحو : حَبَّذا راكِباً زَيْدٌ ، وحَبَّذا زَيْدٌ راكِباً.
أمّا الذمّ فله فعلان أيضاً وهو :
«بِئْسَ» ، نحو : بِئسَ الرَّجلُ زيْدٌ ، وَبِئسَ غُلامُ الرَّجُلِ زيْدٌ ، وَبِئسَ رَجُلاً زيْدٌ. «ساء» نحو : ساء الرَّجُلُ زَيْدٌ ، وساء غُلامُ الرَّجُلِ زَيْدٌ ، وساء رَجُلاً زَيْدٌ ، وساء مثل بئسَ.
القسم الثالث : في الحرف
وقد مضى تعريفه ، وأقسامه سبعة عشر :
____________________________
(١) البقرة : ٢٧١.