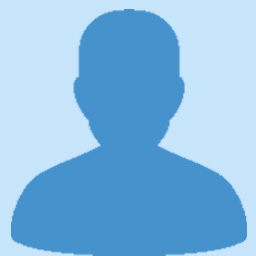وحتّىٰ : وهي مثل «إلىٰ» نحو : نُمْتُ الْبارحَةَ حَتّىٰ الصباحِ. وبمعنى «مع» كثيراً نحو : قَدِمَ الْحَاجُّ حَتَّىٰ الْمُشاةِ. ولا تدخل على غير الظاهر فلا يقال : حَتّاهُ ، خلافاً للمبرّد. وأمّا قول الشاعر :
|
فلا واللهِ لا يبقىٰ اُناس |
|
فتىً حَتّاكَ يابْنَ أبي زيادٍ (١) |
فشاذّ.
وفي : للظرفيّة نحو : زَيْدٌ في الدارِ ، والْماءُ في الْكُوزِ. وبمعنى «عَلىٰ» قليلاً كقوله تعالى : «وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ» (٢).
والباء : وهي للإلصاق حقيقة نحو : بِهِ داءٌ ، أو مجازاً نحو : مَرَرْتُ بِزَيْدٍ ، أي التصق مروري بمكان يقرب منه زيد.
وللاستعانة نحو : كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ.
وللتعدية ك : ذَهَبَ بِزَيْدٍ.
وللظرفية ك : جَلَسْتُ بِالْمَسْجِدِ.
وللمصاحبة نحو : اشْتَرَيْتُ الْفَرَسَ بِسَرْجِهِ.
وللمقابلة نحو : بِعْتُ هذا بِهذا.
وزائدة قياساً في الخبر المنفيّ نحو : ما زَيْدٌ بِقائِمٍ ، وفي الاستفهام نحو : هَلْ زَيْدٌ بقائِمٍ ؟ وسماعاً في المرفوع نحو : بِحَسْبِكَ دِرهمٌ ، «وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ شَهِيدًا» (٣). وفي المنصوب نحو : ألْقىٰ بِيَدِهِ.
واللّام : للاختصاص نحو : الْجُلُّ لِلْفَرَسِ ، والْمالُ لِزَيْدٍ ، وللتعليل
____________________________
(١) يعنى : پس قسم بخدا كه باقى نمى ماند مردمان جوان حتى تو اى پسر ابى زياد. يا آنكه يافت نمى شوند مردمان صاحب سخاوت سواى تو اى پسر ابى زياد. شاهد در دخول حتّى است بر ضمير مخاطب شذوذاً و مجرور بودن آن ضمير به حتى. جامع الشواهد.
(٢) طه : ٧١.
(٣) النساء : ٧٩.