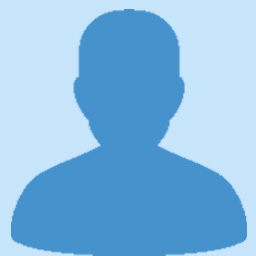اب ہے ان کی علامات۔ کہ اسم کی علامت کیا ہے؟ پہچانیں گے کیسے؟ عربی میں ایک لفظ لکھا ہے قرآن مجید میں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے اور یہ حرف؟ صاحب ہدایہ نے بڑے پیارے انداز میں علامات اسم اور فعل کو بھی بیان فرما دیا ہے۔
کیا؟ کہ یہ علامات اگر ہوں گی تو وہ لفظ، وہ کلمہ اسم ہوگا، اور فلاں فلاں علامت اگر ہوگی تو وہ فعل ہوگا، اور یہ طے ہے کہ جو اسم ہوتا ہے وہ فعل نہیں، جو فعل ہوتا ہے وہ اسم نہیں یا حرف نہیں۔ اب میں اس کو آسان کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ترجمہ کر کے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو ہر ایک کی پھر ساتھ مثال بتاتا جاؤں گا تو آپ کے لیے سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔
"ثم حَدُ الِاسْمِ" اب وہ پہلے بتایا نا کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اب ہر ایک کی تعریف۔ اسم کی تعریف، "حد" کہتے ہیں تعریف کو، اسم کی تعریف کیا ہے؟ "کَلِمَةٌ" اسم وہ کلمہ ہے۔ "تَدُلُّ عَلَىٰ مَعْنًى" جو دلالت کرتا ہے ایک معنی پر، "فِي نَفْسِهَا بذاتہ"، یعنی کسی معنی کو سمجھانے میں، دلالت کرنے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہوتا۔ "غَيْرَ مُقْتَرِنٍ" اور وہ معنی "اَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ" میں سے، "اعنی الْمَاضِیْ وَالْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ" یعنی وہ زمان، وہ معنی "اَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ"، تین زمانے یعنی ماضی، حال اور استقبال میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا، اب کیا کہیں گے؟ یعنی وہ لفظ یہ تو بتاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، معنی کو بتاتا ہے، لیکن معنی کے ساتھ زمانے کو نہیں بتاتا۔
"کَالرَّجُلِ وَعِلْمٍ" بہت توجہ کے ساتھ آغا مزے دار۔ "رَجُلٌ" یہ بھی اسم کی مثال، "عِلْمٌ" اور یہ بھی اسم کی مثال۔
اب سوال یہ ہو گا کہ جناب دو مثالیں دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ جواب دیں گے، "رَجُلٌ" (مرد) یہ ہے "اسمِ ذات" کی مثال، اور "عِلْمٌ" یہ ہے "اسمِ صفت" کی مثال۔ علم ایک صفت ہے جو کسی ذات کے ساتھ ہوتی ہے جبکہ "رَجُلٌ"، "رَجُلٌ" کہتے ہیں مرد کو، مرد ایک خود ذات ہوتی ہے جس کا اپنا خارج میں وجود پایا جاتا ہے۔ صفت ہمیشہ کسی اور کے ساتھ مل کے ہوتی ہے، صفت کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ بہت آسان۔
اب اگلی بات۔ "وَعَلَامَتُهُ" اسم کی علامت کیا ہے؟ علامت اسم کیا ہے؟ بڑی پیاری باتیں ہیں۔ اب آپ اس کو کاپی پر لکھ لیں ایک اور انداز میں تو آپ کو اور زیادہ آسان ہوگا وہ کیا؟ یعنی دو علامتیں اسم کی ایسی ہیں جن کا تعلق ہے ابتداء سے، یعنی وہ اسم کے ابتداء میں آتی ہیں۔ دو علامتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہے انتہا سے کہ وہ اسم کے آخر میں آتی ہیں۔ کتنی ہوگئیں؟ چار۔ آٹھ ہیں وہ کہ جن میں ہر ایک کے ابتداء میں میم آتی ہے۔ بہت پیارا ہے یہ کہ نئی چیز ہے آپ کو مزہ دے گا جب آپ لکھیں کاپی پر تو پھر آپ کو بہت لطف آئے گا۔اچھا وہ کیسے؟ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔
اسم کی علامات
"وَعَلَامَتُهُ" اسم کی علامات۔ اچھا پہلے وہ ترتیب جو میں نے بتائی ہے آپ کاپی میں لکھ لیں، کتاب میں ترتیب اس طرح نہیں ہے۔
۱۔ الف لام
مثلاً دو کا تعلق اسم کے ابتداء سے ہے جیسے الف لام ابتداء میں آ سکتا ہو۔ "رَجُلٌ" کو "اَلرَّجُلُ" پڑھنا۔
۲۔حرف جار
حرف جار ابتداء میں آ سکتا ہو جیسے "رَجُلٌ" کو "بِرَجُلٍ" پڑھنا، "زَيْدٌ" کو "بِزَيْدٍ" پڑھنا۔ ان دو کا تو ابتداء سے ہے۔
۳۔ تنوین
دو کا تعلق انتہا سے ہے۔ آخر میں تنوین کا آنا، "زَيْدٌ"، یہ جو تنوین ہے یہ اسم پر ہوتی ہے فعل پر نہیں ہوتی۔
۴۔تائے تانیث متحرکہ
اسی طرح فرماتے ہیں آخر میں "تائے تانیث متحرکہ" کا آنا۔ او جیسے ہم کہتے ہیں "ضَارِبَةٌ"، تو "ضَارِبَةٌ" یہ بھی اسم ہے فعل نہیں کیونکہ آخر میں "تائے متحرکہ" ہے۔
اچھا باقی رہ گئے آٹھ جو میں نے گزارش کیے ہیں۔کہ جو یعنی ان کے ابتداء میں میم ہوتا ہے، بہت ترتیب سے۔اسم مسند الیہ ہوتا ہے، اسم منصوب ہوتا ہے، اسم مصغر ہوتا ہے، اسم مضاف ہوتا ہے، اسم موصوف ہوتا ہے، اسم منادی ہوتا ہے، اسم مثنی ہوتا ہے، اسم مجموع ہوتا ہے۔ اب دیکھو آٹھ گنیں، ہر ایک کے ابتداء میں میم ہے۔ خوب، یہ تو علیحدہ سے بات تھی اب آپ دیکھیں ان کی مثالیں بھی ان شاءاللہ دیتے ہیں۔
الف لام کی مثال میں نے دے دی "اَلرَّجُلُ"، ابتداء میں حرف جار ہے جیسے "بِزَيْدٍ"۔ تنوین کی مثال "زَيْدٌ"
تائے تانیث متحرکہ کی مثال "ضَارِبَةٌ"۔
اچھا آگے، مسند کی مثال، "زَيْدٌ قَائِمٌ" میں "زَيْدٌ"۔ "قَائِمٌ" مسند، "زَيْدٌ" مسند الیہ۔
"بَغْدَادِيٌّ" منسوب کی مثال یعنی جس کی او نسبت دینا، "بَغْدَادِيٌّ"، یعنی بغداد میں رہنے والا، جس کی نسبت بغداد کی طرف ہو، بغدادی ہو گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں لاہوری ہے۔ فلاں پشاوری ہے۔ فلاں پنجابی ہے۔ یہ جو آخر میں یا ہوتی ہے یہ نسبت والی ہوتی ہے نا اس کو منسوبی کہتے ہیں۔
مصغر کی مثال جیسے "رَجُلٌ" سے "رُجَيْلٌ"۔ اسم کوئی تصغیر ہو سکتی ہے، فعل کی نہیں ہو سکتی۔
اچھا مضاف، "غُلامُ زَيْدٍ"، "غُلام" اسم ہے یہ مضاف ہوا ہے "زَيْدٍ" کی طرف، جبکہ فعل یا حرف مضاف نہیں ہوتا۔
موصوف، "رَجُلٌ کَرِيْمٌ"، "رَجُلٌ" موصوف ہے، "کَرِيْمٌ" وہ اس کی صفت ہے، تو "رَجُلٌ" موصوف ہے یہ اسم ہے فعل کبھی موصوف نہیں ہوتا یا حرف۔
منادی، جیسے "یَا اللّٰهُ"۔ "اللّٰهُ" اسم ہے، "یَا اللّٰهُ" تو کہہ سکتے ہیں، "یَا ضَرَبَ" نہیں کہہ سکتے۔ فعل منادی واقع نہیں ہوتا۔
مثنی، "رَجُلَانِ"، "رَجُلٌ" کی تثنیہ "رَجُلَانِ"۔
مجموع یعنی جمع، جیسے "رَجُلٌ" کی جمع "رِجَالٌ"۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے علامات اسم، یعنی یہ فقط اسم میں، فعل یا حرف میں یہ نہیں ہیں۔
اسم کی علامات (کتاب کی ترتیب)
اب کتاب کا ترجمہ۔ مثالیں ساری کاپی پر لکھ لیں گے تو آپ کے لیے پھر اور آسان ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں۔ "وَعَلَامَتُهُ" اسم کی علامت کیا ہے؟
۱۔إِخْبَارُ عَنْهُ
"أَنْ يَصِحَّ الْإِخْبَارُ عَنْهُ" اس سے خبر دینا صحیح ہے، یعنی وہ مسند الیہ بن سکتا ہے، جیسے جیسے میں نے مثال دی تھی "زَيْدٌ قَائِمٌ"، "زَيْدٌ" مبتدا تھا، "قَائِمٌ" خبر تھی، "زَيْدٌ" مسند الیہ ہے، "قَائِمٌ" مسند ہے، یعنی "زَيْدٌ" سے خبر دینا، یعنی "زَيْدٌ" مبتدا، یعنی آپ یوں کہیں گے کہ اسم مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔
۲۔الْإِضَافَةُ
"وَالْإِضَافَةُ" اسی طرح دوسری علامت اب ترتیب سے لکھتے جائیں۔ اسم کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس کو مضاف، اضافت صحیح ہے، "نَحْوَ غُلامُ زَيْدٍ"۔ "غُلام" اسم ہے جو مضاف ہو کر استعمال ہوا ہے۔
۳۔دُخُولُ لَامِ التَّعْرِيفِ
"وَدُخُولُ لَامِ التَّعْرِيفِ" تیسری علامت، اسم پر الف لام تعریف کا داخل ہو سکتا ہے، "کَالرَّجُلِ" جیسے "رَجُلٌ" پر "اَلرَّجُلُ"۔
۴۔الْجَرُّ
"وَالْجَرُّ" اسم پر حرف جار داخل ہو سکتا ہے، جیسے میں نے مثال دی تھی "بِزَيْدٍ"۔
۵۔التَّنْوِينُ
اسم پر تنوین آ سکتی ہے "وَالتَّنْوِينُ"، جیسے ہم نے کیا کہا تھا "زَيْدٍ"، دال پر تنوین ہے یا "زَيْدٌ" اس کو تنوین کہتے ہیں۔
۶۔التَّثْنِيَةُ
"وَالتَّثْنِيَةُ وَالْجَمْعُ" اسم تثنیہ ہوتا ہے جیسے "رَجُلٌ" سے "رَجُلَانِ"۔
۷۔الْجَمْعُ
"وَالْجَمْعُ" اسم جمع ہوتا ہے جیسے "رَجُلٌ" سے "رِجَالٌ"۔
۸۔النَّعْتُ
"وَالنَّعْتُ" اسم صفت واقع ہو سکتا ہے۔
۸۔التَّصْغِيْرُ
"وَالتَّصْغِيْرُ" اسم کی تصغیر ہو سکتی ہے، او جیسے "رَجُلٌ" سے "رُجَيْلٌ"۔
۹۔النِّدَاءُ
"وَالنِّدَاءُ" اسی طرح اس پر حرف ندا ہو، یعنی منادی واقع ہو سکتا ہے جیسے "یَا اللّٰهُ"۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ علامات ہو گئیں اس کی۔
آگے فرماتے ہیں۔ "فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الِاسْمِ" یہ ساری کی ساری اسم کی خصوصیات ہیں، یعنی یہ چیزیں فقط اسم کے ساتھ خاص ہیں، فعل یا حرف کے ساتھ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا آغا، یہ بات یہاں ختم۔
فرماتے ہیں "وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ" یہ جو ہم نے ابتداء میں کہا تھا کہ اسم سے خبر دینا صحیح ہے، کیا مطلب؟ وہ بتا رہے ہیں اس "اخبر عن" کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اسم سے بارے میں خبر دینا صحیح ہے، فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے "أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ" اس کا مطلب ہے یعنی اسم "محکوم علیہ" واقع ہو سکتا ہے، یعنی اسم پر کوئی حکم لگایا جا سکتا ہے، کیوں؟ "لِكَوْنِهِ فَاعِلًا" چونکہ یا یہ فاعل ہوگا، یا مفعول ہوگا، یا مبتدا ہوگا، تو یہ فاعل ہو، مفعول ہو یا مبتدا ہو یہ "محکوم علیہ" ہوتا ہے اور بعد میں ان پر خبر ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں "زَيْدٌ قَائِمٌ"، اس میں "زَيْدٌ" مبتدا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں۔ "زَيْدٌ مَضْرُوبٌ"، "محکوم علیہ"، یعنی "زَيْدٌ" پر کیا ہے؟ خبر دی جا رہی ہے کس بات کی کہ "زَيْدٌ" کو مارا گیا ہے، یا ہم کہتے ہیں "زَيْدٌ ضَارِبٌ"، یعنی خبر دی جا رہی ہے کہ "زَيْدٌ" فاعل ہے، کیا مطلب؟ یعنی کہ "زَيْدٌ" مارنے والا ہے۔
اسم،اسم کیوں کہلاتا ہے؟
اب آخر میں فرماتے ہیں ایک جملہ۔ وہ جملہ یہ ہے کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ اسم مشتق "سمو" سے ہے، "سمو" کہتے ہیں بلندی کو، برتری کو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مشتق "وسم" سے ہے، "وسم" کہتے ہیں علامت کو، چونکہ یہ اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے۔
صاحب ہدایہ کی رائےسمو سے اشتقاق
صاحب ہدایہ اپنا نظریہ بنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں۔ "وَيُسَمَّى اسْمًا" میرے نزدیک اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے؟ اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے؟ "لِسُمُوِّهِ عَلَى قِسْمَيْهِ" اس لیے کہ یہ اپنی دونوں دونوں باقی قسمیں یعنی فعل اور حرف سے بلند ہوتا ہے، "لِسُمُوِّهِ" یعنی یہ بلند ہوتا ہے، ہول ہوتا ہے اس لیے۔ یعنی گویا ان کے نزدیک اسم "سم" یعنی بلندی سے مشتق ہے۔
وسم سے اشتقاق کی تردید
آگے فرماتے ہیں۔ "لَا لِكَوْنِهِ وِسْمًا عَلَى الْمَعْنَى" نہ اس لیے، نہ یہ کہ یہ چونکہ اپنے معنی پر علامت "وسم" کہتے ہیں علامت کو، وہ جو میں نے گزارش کی کہ بعض کہتے ہیں کہ اسم مشتق "وسم" سے ہے، یعنی اس اصل میں "وسم" تھا، "وسم" کہتے ہیں علامت کو، چونکہ یہاں اپنے معنی پر علامت ہے۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ "وسم" سے مشتق نہیں، بلکہ یہ "سم" یعنی بلندی والے معنی سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟
سمو اور وسم کی وضاحت
"سمو"، "سم" یعنی بلندی اور "وسم" یعنی علامت۔