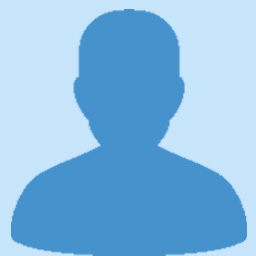فصل : الاسم إمّا مذكّر وإمّا مؤنّث ، والمؤنّث ما فيه علامة التأنيث لفظاً أو تقديراً والمذكّر هو ما بخلافه.
وعلامة التأنيث ثلاثة : التاء كطَلْحَة ، والألف المقصورة كحُبلىٰ ، والممدودة كحَمْراء وصَفْراء. والمقدّر إنّما هو التاء فقط كأرْض ودار ، بدليل ارَيْضَة ودُوَيْرَة ، ثمّ المؤنّث على قسمين :
حقيقيّ : وهو ما بازائه حيوان مذكّر كامرأة وناقة.
ولفظيّ : وهو مجازيّ بخلافه كظلْمَة وعَيْن. وقد عرفت أحكام الفعل إذا اُسند إلى المؤنّث فلا نعيدها.
فصل : المثنّى : اسم ما اُلحق بآخره ألفٌ أو ياءٌ مفتوح ما قبلها ونون مكسورة ليدلّ على أنّ معه آخر مثله نحو : رَجُلانِ رفعاً ، ورَجُلَيْنِ نصباً وجرّاً ، هذا في الصحيح.
أمّا في المقصور : فإن كان الألف منقلبة عن الواو وكان ثلاثيّاً ردّ إلى أصله ك : عَصَوان في عَصا.
وإن كانت عن ياء ، أو عن واو ، وكانت أكثر من الثلاثي ، أو ليس منقلبة عن شيء تقلب ياء ك : رَحَيانِ ومَلْهَيانِ وحُبارَيان.
وأمّا الممدودة : فإن كانت همزته أصليّة كقُرّاء تثبت ك : قُرّاءان ، وإن كانت للتأنيث تقلب واواً كحَمْراوان ، وإن كانت بدلاً من واو أو ياء من الأصل جاز فيه الوجهان ك : كساوانِ وكَساءان ، ورَداوان ورداءان.
ويجب حذف نونه عند الإضافة تقول : جاءَ غُلاما زَيْدٍ.
ويحذف تاء التأنيث في الخصية والإلية خاصّة تقول : خُصْيانِ وإلْيانِ لأنّهما متلازمان فكأنّهما تثنية شيءٍ واحد لا زوج.
واعلم أنّه إذا
اُريد إضافة المثنّى إلى المثنّى يعبّر عن الأوّل بلفظ الجمع