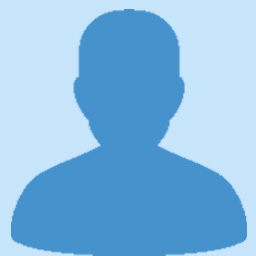ويجوز حذف العائد من اللفظ إن كان مفعولاً نحو : قام الّذي ضربتُ ، أي الّذي ضَرَبْتُهُ.
واعلم أنّ «أيّا وأيَّة» معربة إلّا إذا حذف صدر صلتها كقوله تعالى : «ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَـٰنِ عِتِيًّا» (١) ، أي هو أشدُّ.
النوع الرابع : أسماء الأفعال
كلّ اسم بمعنى الأمر والماضي ك : رُوَيْدَ زيداً ، أي أمْهِلْهُ ، وهَيْهاتَ زَيْدٌ ، أي بَعُد ، وإن كان على وزن فَعالِ بمعنى الأمر ، وهو من الثلاثي فهو قياسيّ كنزال بمعنى انزل وتَراكِ بمعنى اترك. وقد يلحق به فَعال مصدراً معرفة ، كفَجار بمعنى الفجور ، أو صفة للمؤنّث نحو : يا فَساقِ بمعنى فاسقة ، ويالكاع بمعنى لاكعة ، أو عَلَماً للأعيان المؤنّثة كَقطامِ وغَلابِ وحَضارِ. وهذه الثلاثة الأخيرة ليست من أسماء الأفعال وإنّما ذكرت هاهنا للمناسبة.
النوع الخامس : الأصوات
وهو كلّ اسم حُكِي به صوت ، ك : قاق لصوت الغراب ، أو لصوت يصوّت به للبهائم ك : نِخْ لإناخة البعير ، وطاقْ حكاية الضرب ، وطَقْ حكاية وَقْع الحجارة بعضها ببعض.
النوع السادس : المركّبات
وهو كلّ اسم ركّب من الكلمتين ليس بينهما نسبة ، أي ليس بينهما
____________________________
(١) مريم : ٦٩.