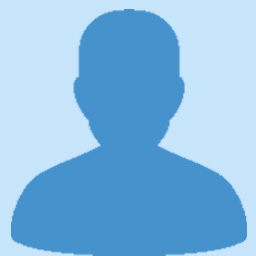خبر إِنَّ
"وَاعْلَمْ أَنَّ إِنَّ الْمَكْسُورَةَ يَجُوزُ دُخُولُ اللَّامِ عَلَى خَبَرِهَا"۔ گزشتہ درس میں گزارشات کی تھیں کہ "أَنَّ" اور "إِنَّ" چونکہ یہ حروفِ مشبہ بالفعل میں دو علیحدہ علیحدہ حرف ہیں۔ پھر یہ بھی گزارش کی تھی کہ چار مقامات پر "إِنَّ" پڑھنا واجب ہے اور سات مقامات پر "أَنَّ" پڑھنا واجب ہے۔ یہ بھی بتایا تھا کہ "إِنَّ" معنی جملے میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا فقط تاکید کرتا ہے جبکہ "أَنَّ" اسم و خبر کے ساتھ مل کر مفرد میں چلا جاتا ہے۔ اب اسی سے کچھ مربوط مسائل اور ہیں جو "إِنَّ" اور "أَنَّ" کے گویا کہ احکام میں سے شمار ہوتے ہیں۔ یہ احکام میں سے یہ ہے کہ "إِنَّ" کی خبر پر، "إِنَّ" کی خبر پر، لام کا داخل کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ "إِنَّ" کی خبر پر اگر آپ لام داخل کرنا چاہیں جیسے "إِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ" اس لام کو لامِ مزحلقہ کہتے ہیں تو یہ ہے جائز ہے، واجب نہیں، جائز ہے کہ آپ اس کی خبر پر لام داخل کر دیں جیسے میں نے کہا "إِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ"۔
تخفیف إِنَّ
دوسرا حکم "وَ قَدْ تُخَفَّفُ"۔ کبھی "إِنَّ" مخفف ہو جاتا ہے یعنی اس کی شد کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ "إِنَّ" کی بجائے "إِنْ" پڑھا جاتا ہے۔ "إِنَّ" کی بجائے "إِنْ"۔ بہت، اب یہ حکم ہے۔ کیا؟ اگر کبھی "إِنَّ" کو مخفف کر کے "إِنْ" پڑھا جائے گا تو جو "إِنْ"، "إِنَّ" سے مخفف ہو گا اس "إِنْ" کی خبر پر لام داخل کرنا واجب ہو گا۔ بہت توجہ آغا جان۔ "وَ قَدْ تُخَفَّفُ" یعنی کبھی کبھی "إِنَّ" مخفف ہوتا ہے یعنی "إِنَّ" نہیں ہوتا بلکہ "إِنْ" ہوتا ہے۔ جب بھی یہ "إِنَّ" مخفف ہو گا اس کو کہتے ہیں "مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ"۔ "إِنَّ" کی بجائے "إِنْ" ہو گا "فَيَلْزَمُهَا اللَّامُ" پھر اس کی خبر پر لام کا داخل کرنا لازم ہو گا، واجب ہو گا جیسے آیت مجیدہ ہے۔ "وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ" یہ "إِنْ" مخففہ ہے، اصل میں "إِنَّ" ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس کی خبر پر لام کو قرآن مجید میں لایا گیا۔ لہٰذا "لَيُوَفِّيَنَّهُمْ" یہاں لام لانا لازم ہے۔
الغاء إِنَّ
تیسرا حکم یہ ہے "وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ إِلْغَاؤُهَا"۔ یہ ایک باقاعدہ حکم ہے۔ کہ اگر کبھی "إِنَّ" مخفف ہو جائے اور "إِنَّ" کی بجائے "إِنْ" ہو جائے، مخفف ہو جائے، ہے انہی حروفِ مشبہ بالفعل سے لیکن ہے مخفف، تو اس کو عمل سے ملغی کرنا بھی جائز ہے کہ اس وقت وہ جو اس کا عمل ہوتا ہے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دینا، اس وقت اس کو ملغی کر دیں۔ اس کا وہ عمل باطل کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے قرآن میں اس کا بھی ایک شاہد موجود ہے وہ ہے "وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ"۔ "إِنْ كُلٌّ" پڑھا گیا ہے "كُلًّا" نہیں پڑھا گیا۔ تو پس "إِنْ" بہت توجہ کے ساتھ، جب "إِنْ" مخففہ ہو جائے گا تو اس وقت اس کے عمل کو ملغی کرنا بھی جائز ہے۔ پہلا حکم کیا تھا؟ کہ "إِنَّ" کی خبر پر لام کو داخل کرنا جائز ہے۔ دوسرا، اگر یہ "إِنَّ" "إِنْ" بن جائے مخفف ہو جائے تو خبر پر لام کو داخل کرنا واجب ہے۔ نمبر تین، اگر یہ مخفف ہو جائے تو اس کے عمل کو ملغی کرنا بھی جائز ہے۔
چوتھا حکم اس کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے۔ "وَيَجُوزُ دُخُولُهَا عَلَى الْأَفْعَالِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ"۔ بہت توجہ۔ یعنی اس "إِنْ" کو، اس "إِنْ" مخففہ کو ان افعال پر داخل کرنا کہ جن کو افعالِ ناسخہ کہتے ہیں ہم طور پر، افعال پر داخل کرنا جو خود مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ اور جیسے افعالِ ناقصہ وغیرہ۔ تو ان پر اس "إِنْ" مخففہ کو داخل کرنا بھی جائز ہے۔ یعنی جو افعال مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں ان افعال پر اس "إِنْ" مخففہ کو داخل کرنا جائز ہے۔ جس، جیسے آیت مجیدہ ہے۔ "وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ"۔ اب کنت آپ نے دیکھا یہ افعالِ ناقصہ کا ہے، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے تو جائز ہے کہ ہم کنت سے پہلے ہی اس "إِنْ" مخففہ کو لگا دیں جیسے قرآن میں یہ شاہد موجود ہے۔ اسی طرح "إِنَّا نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ"۔ "وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ"۔
تخفیف أَنَّ
یہ یہاں ختم ہو گئے اس کے احکام۔ آگے فرماتے ہیں اسی طرح کچھ احکام ہیں جو "أَنَّ" سے مربوط ہیں۔ "أَنَّ" سے مربوط پہلا حکم "أَنَّ الْمَفْتُوحَةَ قَدْ تُخَفَّفُ"۔ جیسے "إِنَّ" کبھی مخففہ من المثقلہ ہو کر "إِنْ" بن جاتا تھا یہ "أَنَّ" بھی کبھی کبھی مخفف ہو کر "أَنْ" بن جاتا ہے۔ جب "أَنَّ" مخفف ہو گا تو یہ بن جائے گا "أَنْ" ان جب بن جائے گا تو پھر"فَحِينَئِذٍ"کامعنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی حِینَ اِذ کَانَ کَذَا، کیا مطلب؟ یعنی جب یہ "أَنَّ" مخفف ہو کر "أَنْ" بن جائے گا، جب "أَنَّ" "أَنْ" ہو جائے گا مخفف ہو جائے گا "يَجِبُ إِعْمَالُهَا فِي ضَمِيرِ الشَّأْنِ" تو پھر واجب ہے کہ یہ ایک ضمیر شانِ مقدرہ میں عمل کرے۔ ایک ضمیر شانِ مقدرہ میں عمل کرے، یہ واجب ہے۔ پھر نتیجہ؟ "فَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْاِسْمِيَّةِ كَانَتْ أَوْ فِعْلِيَّةً"۔ پس یہ "أَنْ" جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے، جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتا ہے لیکن مخفف ہونے کی صورت میں واجب ہے کہ یہ ایک ضمیر شانِ مقدر میں عمل کرے جیسے "بَلَغَنِي أَنْ زَيْدٌ"، "بَلَغَنِي أَنْ زَيْدٌ قَائِمٌ" یہ اسمیہ کی مثال یا "بَلَغَنِي أَنْ قَدْ قَامَ زَيْدٌ"۔ یہ ہو گئی فعل کی مثال۔
سَوْف، قَدْ یا حرف نفی کا دخول
"وَيَجِبُ دُخُولُ السِّينِ وَسَوْفَ أَوْ قَدْ أَوْ حَرْفِ النَّفْيِ عَلَى الْفِعْلِ" فرماتے ہیں واجب ہے، بہت توجہ کے ساتھ، کیا واجب ہے؟ واجب یہ ہے کہ جب "أَنْ" مخففہ من المثقلہ ہو گا اور یہ کسی جملہ فعلیہ پر داخل ہو گا تو اس وقت واجب ہے کہ اس فعل پر "سِين"، "سَوْفَ"، "قَدْ" یا حرفِ نفی داخل کیا جائے۔ جیسے "عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ" اب ان آیا، اب "يَكُونُ" سے پر پہلے سین کو لگایا گیا۔ "وَضَمِيرُ الْمُسْتَتِرِ اِسْمُ أَنَّ"۔ تو پس درحقیقت اس میں جو ضمیر مستتر ہے وہ "أَنَّ" کا اسم ہے اور جملہ بعد والا وہ اس کی خبر ہو گا۔ یہ تو چند احکام تھے جو "أَنَّ" اور "إِنَّ" سے مربوط تھے۔
آگے فرماتے ہیں حروفِ مشبہ بالفعل میں ایک ہے "كَأَنَّ"۔ یہ آسان ہے کئی دفعہ گزارش کی ہے۔
كَأَنَّ
"كَأَنَّ لِلتَّشْبِيهِ"۔ "كَأَنَّ" آتا ہے تشبیہ کے لیے یعنی یہ بتانے کے لیے کہ وہ چیز اس چیز کے ساتھ کسی صفت میں شریک ہے۔ تشابہ یہی ہوتا ہے نا تشبیہ دینے کے لیے جیسے "كَأَنَّ زَيْدًا الْأَسَدُ"۔ "زَيْدًا" اسم ہو گیا "الْأَسَدُ" اس کا کی خبر ہو گئی۔ "كَأَنَّ" گویا کہ زید شیر ہے۔ یعنی زید شیر کی طرح ہے، زید کو شیر کے ساتھ شباہت دی جا رہی ہے۔ "هُوَ مُرَكَّبٌ" یہ "كَأَنَّ" یہ مرکب ہے "كَافِ تَشْبِيه" اور "إِنَّ" سے یعنی اصل میں ہے "كَإِنَّ"۔ کافِ تشبیہ علیحدہ ہے اور "إِنَّ" علیحدہ ہے۔ "إِنَّ" اور کافِ تشبیہ کو ملا کر بن گیا "كَأَنَّ"۔ تو پھر سوال ہو گا جناب اگر اصل میں "إِنَّ" ہے تو پھر "كَإِنَّ" پڑھیں نا، پھر اس کو "كَأَنَّ" کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ "إِنَّ" اور "أَنَّ" میں تو فرق ہے۔ جواب: "إِنَّمَا فُتِحَ" ٹھیک ہے یہ "إِنَّ" اور کافِ تشبیہ سے مل کر بنا ہے لیکن اب ہم ان کا "إِنَّ" کی بجائے "كَأَنَّ" پڑھ رہے ہیں۔ اب جو ہم ہمزے کو فتح دے رہے ہیں اس کی وجہ، وجہ یہ ہے "لِتَقَدُّمِ الْكَافِ عَلَيْهِ"۔ چونکہ کافِ تشبیہ اس پر مقدم ہے۔ کافِ تشبیہ اس پر مقدم ہے لہٰذا "إِنَّ" کے کسرے کو فتح میں تبدیل کر کے یہ بن گیا "كَأَنَّ"۔ گویا اصل میں عبارت یوں تھی "إِنَّ زَيْدًا كَالْأَسَدِ"۔ "إِنَّ زَيْدًا كَالْأَسَدِ"۔ تو ہم نے کاف اور اس کو جب ملایا تو یہ بن گیا "كَأَنَّ"۔"وَ قَدْ يُخَفَّفُ"۔ اور کبھی کبھی یہ بھی مخفف ہو جاتا ہے یعنی "كَأَنَّ" بھی مخفف ہو جاتا ہے۔ اس کی شد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر "كَأَنَّ" مخفف ہو جائے گا تو اس وقت یہ عمل سے ملغی ہو جائے گا۔ یعنی اس نے جو عمل کرنا ہوتا تھا وہ عمل اس کا باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس وقت اس پر یہ عمل نہیں ہو گا۔عمل سے خالی جیسے "كَأَنْ زَيْدٌ أَسَدٌ"۔
لَكِنَّ
"وَلَكِنَّ"۔ حروفِ مشبہ بالفعل میں سے تیسرا، "لَكِنَّ"۔ "لَكِنَّ" کس کے لیے آتا ہے؟ "لَكِنَّ" آتا ہے استدراک۔ استدراک یعنی کسی چیز کو درک کرنا، کسی چیز کو پا لینا۔ یعنی سابقہ کلام میں ایک بندے کو وہم پیدا ہوتا ہے بعد میں اس وہم کو یہ پا لیتا ہے سمجھ آتی ہے پھر اس کو دور کرنے کے لیے "لَكِنَّ" لگایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ استدراک کے لیے ہے۔ یعنی جو وہم پیچھے ہوا تھا "لَكِنَّ" کے ذریعے اس نے اس وہم کا تدارک کیا ہے، اس وہم کو دور کیا ہے۔ اب جب یہ استدراک یعنی کسی کلام میں وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، بڑی پیاری سی بات۔ "يَتَوَسَّطُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ فِي الْمَعْنَى"۔ اب ضروری ہے کہ یہاں جملے بھی دو ہونے چاہئیں، کلام بھی دو ہونے چاہئیں۔ ایک وہ ہو جس میں وہم ہو اور ایک وہ ہو "لَكِنَّ" کے بعد جو اس وہم کو دور کرے، جس میں وہ وہم دور کیا گیا ہو۔ تو ظاہر ہے پھر یہاں دو کلامیں، دو جملے درکار ہوں گے کہ ایک میں وہم، جو غلطی ہو گئی اور دوسری کلام وہ جس میں اس کا تدارک کیا گیا۔ "وَيَتَوَسَّطُ"۔ پس اس کا مطلب ہے "لَكِنَّ" ہمیشہ دو کلاموں کے درمیان میں آتا ہے "يَتَوَسَّطُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ"۔ دو کلاموں کے درمیان آتا ہے۔ اگلا جملہ، کلامین کی صفت ہے۔ "مُتَغَايِرَيْنِ فِي الْمَعْنَى"۔ وہ دونوں جملے، وہ دونوں کلامیں معنی کے لحاظ سے متغایر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو مطلب پہلے جملے کا ہے دوسرے کا بھی وہی ہو، نہ نہ بلکہ ان کے معنی میں تغایر ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ مثال: "مَا جَاءَنِي الْقَوْمُ"۔ میرے پاس نہیں آئی قوم۔ اب اس کا مطلب کیا ہو گا؟ اس سے وہم ہوا۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا۔ لیکن بعد میں کہتا ہے "لَكِنَّ عَمْرًا جَاءَ"۔ لیکن امر آیا۔ اب اس "لَكِنَّ" نے وہ جو "مَا جَاءَنِي الْقَوْمُ" سے ایک وہم پیدا ہو رہا تھا کہ کوئی فرد بھی نہیں آیا "لَكِنَّ" نے اس وہم کو دور کیا، اس کا تدارک کیا ہے کہ نہیں نہیں صرف امر میرے پاس آیا۔ اب پہلی کلام تھی نہ آنے کے بارے میں اور دوسری ہے آنے کے بارے میں۔ لہٰذا معناً یہ دونوں جملے آپس میں متغایر ہیں، پہلے میں نفی تھا دوسرے میں اثبات ہے۔ اسی طرح اگلی مثال "غَابَ زَيْدٌ لَكِنَّ بَكْرًا حَاضِرٌ"۔ زید غائب ہے لیکن بکر حاضر ہے۔ اب آپ دیکھیں وہاں "لَكِنَّ" سے پہلے جملہ ہے کہ زید غائب ہے۔ اب وہاں سے وہم ہو اس کا مطلب ہے پھر بکر بھی اس کے ساتھ غائب ہو گا، "لَكِنَّ" کہتے ہیں نہیں نہیں بکر حاضر ہے۔ اب معنی میں بھی فرق ہے اور اس نے اسی وہم کو بھی دور کیا۔
"يَجُوزُ مَعَ الْوَاوِ"۔ اس "لَكِنَّ" کے ساتھ اگر واو کو لگا دیا جائے تو بھی یہ جائز ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں "قَامَ زَيْدٌ وَلَكِنَّ عَمْرًا قَاعِدٌ"۔ یعنی "لَكِنَّ" سے پہلے اگر واو کو لگا دیں تو بھی جائز ہے۔ آگے فرماتے ہیں اس کا حکم اور یہ ہے "وَ قَدْ تُخَفَّفُ"۔ جیسے "إِنَّ" مخفف ہوتا تھا، "أَنَّ" ہوتا تھا، "كَأَنَّ" ہوتا تھا یہ "لَكِنَّ" بھی کبھی مخفف ہو جاتا ہے یعنی "لَكِنَّ" سے "لَكِنْ" بن جاتا ہے۔ جب "لَكِنَّ" مخفف ہو گا "فَتُلْغَى" اس کا عمل ملغی کر دیا جائے گا یعنی اس کا عمل باطل ہو گا پھر یہ وہ ناصب اور رافع نہیں رہے گا جیسے ہم کہتے ہیں "مَشَى زَيْدٌ لَكِنْ بَكْرٌ عِنْدَنَا"۔ اب "لَكِنْ بَكْرًا" نہیں پڑھنا چونکہ "لَكِنْ" یہ مخفف ہے اور اپنا عمل اس کا ختم ہو گیا۔
لَيْتَ
"لَيْتَ" آتا ہے تمنی کے لیۓ، جیسے "لَيْتَ هِنْدًا عِنْدَنَا"۔ کاش ہندہ ہمارے پاس ہوتی۔ فرّا کہتا ہے کہ "لَيْتَ زَيْدًا قَائِمٌ" کی بجائے "لَيْتَ زَيْدًا قَائِمًا" کہنا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے "لَيْتَ" بمعنی "أَتَمَنَّى" ہے۔ یہ فعل کے معنی میں ہے اور فعل جب آ جائے گا تو "زَيْدًا قَائِمًا" یہ اس کے مفعول بن جائیں گے۔ لہٰذا "لَيْتَ زَيْدًا قَائِمًا" کی بجائے "لَيْتَ زَيْدًا قَائِمًا" بھی اگر پڑھ جائے "لَيْتَ" بمعنی "أَتَمَنَّى" کے ہو گا یہ معنی فعل کو متضمن ہے اور اگلے دو اس کے مفعول ہوں گے۔ خب، یہ اس کا نظریہ ہے۔ "لَيْتَ"، تمنی، کسی شئ کی خواہش کرنا، اس کو پسند کرنا، اس کو چاہنا۔
لَعَلَّ
"لَعَلَّ"۔ حروفِ مشبہ بالافعل میں سے ایک ہے "لَعَلَّ"۔ "لَعَلَّ" آتا ہے ترجی کے لیۓ۔ ترجی کا معنی کیا؟ یعنی امید کے لیے۔ اب ترجی اور تمنی میں ایک تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہ "لَيْتَ" بسا اوقات وہاں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جس کا ملنا، جس کا حصول ممکن نہ ہو۔ اور جیسے مشہور مثال ہے "لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ" کاش جوانی پلٹ آتی۔ "لَيْتَ" وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جس کے فی الحال حاصل ہونے، بہرحال اس میں ہو۔ "لَعَلَّ" ترجی کے لیے آتا ہے یعنی ترجی سے مراد کیا؟ یعنی ایسی کسی چیز کی امید کرنا البتہ ایسی چیز کی امید کرنا کہ جو ہو بھی سکتی ہو، جس کے حصول کے مواقع میسر ہوں، صلاحیت میسر ہو۔ جیسے فرماتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے "أُحِبُّ الصَّالِحِينَ" میں صالح نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں، "وَلَسْتُ مِنْهُمْ" حالانکہ میں صالحین میں سے، نیکوں میں سے نہیں ہوں۔ آگے کہتا ہے "لَعَلَّ اللهَ يَرْزُقَنِي صَلَاحًا"۔ شاید اللہ مجھے بھی نیکی کی یعنی اصلاح کا رزق عطا فرما دے۔ یعنی میرے اندر صلاحیت تو ہے میں نیک بن سکوں لیکن ممکن ہے کہ اللہ مجھے دے۔ "لَعَلَّ اللهَ" اب یہاں "لَعَلَّ" اس ترجی اور امید کے لیے استعمال ہوا۔
لَعَلَّ بطور حروف جار
اب دو تین لفظ ہیں اسی طرح اللہ کے بارے میں۔ بعض لوگ "لَعَلَّ" کو حروفِ جار میں استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ "لَعَلَّ زَيْدٍ قَائِمٌ" یعنی شوّل "الْجَرُّ بِهَا" فرماتے ہیں "لَعَلَّ" کا جار واقع ہونا اور "لَعَلَّ" کے ذریعے بعد والے اسم کو جر دینا شاذ ہے۔ "الشَّاذُّ كَالْمَعْدُومِ"۔ اس "لَعَلَّ" کو بعض لغات، بعض لغتوں میں، بعض قبائل اس کو عربی میں "لَعَلَّ" کی بجائے "عَلَّ" پڑھتے ہیں، کچھ "أَنَّ" پڑھتے ہیں، کچھ "عَنَّ" پڑھتے ہیں، کچھ "لَغَنَّ" پڑھتے ہیں، کچھ "لَعَنَّ" پڑھتے ہیں۔ مبرد کہتا ہے کہ نہیں، یہ "لَعَلَّ" اصل میں "عَلَّ" ہے اور بعد میں اس میں لام اضافی کی گئی اور یہ بن گیا "لَعَلَّ"۔ باقی جتنی بھی ہیں "عَلَّ" یا "أَنَّ" وغیرہ وہ ساری اس کی فروعات میں سے ہیں، اصل یہی ہے۔ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ۔