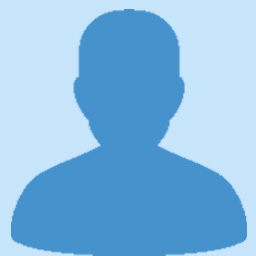یاء متکلم کی طرف اضافت کا بیان
"وَاعْلَمْ" آگے ایک اور نکتہ جو اسی سے مربوط ہوتا ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی اسمِ صحیح یا جاری مجریٰ صحیح ہو۔ صحیح کی تعریف میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ نحوی صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں واو یا یاء نہ ہو۔ اور صرفی تو کہتے تھے کہ جس کے تین حروف میں سے کسی کے مقابل میں حرف علت نہ ہو، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں وا یا یاء نہ ہو اس کو صحیح کہتے ہیں اور جاری مجریٰ صحیح کسے کہتے تھے یہ والے؟ کہ جس کے آخر میں وا یا یاء ہو اور اس کا ماقبل کیا تھا؟ ماقبل ساکن ہو۔ جیسے "دَلْوٌ"، "ظَبْيٌ" تھا۔
فرماتے ہیں: "وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا أَضَفْتَ الِاسْمَ الصَّحِيحَ"، اگر آپ کسی اسمِ صحیح کو مضاف کریں یاء متکلم کی طرف آگے آ رہا ہے۔ "أَوِ الْجَارِيَ مَجْرَى الصَّحِيحِ"، یا کسی ایسے اسم کو جو صحیح کا قائم مقام ہو ، فرماتے ہیں: اگر آپ کسی اسمِ صحیح یا جاری مجریٰ صحیح کو مضاف کرنا چاہتے ہیں "إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ"، یاء متکلم کی طرف، بہت توجہ، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں :اس کا طریقہ یہ ہوگا "كَسَرْتَ آخِرَهُ"، اس اسم کے آخر کو کسرہ دیں گے اور "وَسَكَّنْتَ الْيَاءَ" اور یاء کو ساکن کر دیں گے "أَوْ فَتَحْتَهَا" یا اس کو فتحہ دیں گے۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔اب ذرا غور، کیسے آخر کو کسرہ دے کر یاء کو ساکن کریں، جیسے غلامی، غلام مضاف یاء مضاف الیہ۔ دلوی، دلو مضاف یاء مضاف الیہ یا ظبیی۔ یا پھر اس کے آخر کو آپ فتحہ دیں گے۔ اب اس کی مثالیں آ رہی ہیں جیسے عصایا، رحایا۔
فرماتے ہیں: "وَإِنْ كَانَ آخِرُ الِاسْمِ أَلِفًا" تو اس میں اگر آخرِ اسم میں الف ہو، جیسے عصا آخر میں الف ہے، یا رحا آخر میں الف ہے۔ فرماتے ہیں: اگر آخر میں الف ہو تو اس الف کو ثابت رکھیں گے یعنی اس الف کو گرائیں گے نہیں، اس الف کو حذف نہیں کریں گے، اسی طرح جیسے ہے باقی رکھیں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں عصایا، عصا کے بعد الف ہے موجود ہے۔ یا رحا میں ہے رحایا، یہ موجود ہے۔ البتہ ہذیل نحوی وہ کہتا ہے کہ نہیں عصایا اور رحایا نہیں بلکہ اس کو پڑھیں گے عصیّا اور رحیّا۔ یعنی وہ اس الف کو بھی یاء میں تبدیل کرتا ہے پھر یاء کو یاء میں ادغام کرتا ہے پھر اس کے ماقبل کو کسرہ دیتا ہے یاء کی مناسبت کے لیے۔
اگلا حکم: "وَإِنْ كَانَ الِاسْمُ يَاءً مَقْصُورًا مَا قَبْلَهَا" اگر اس اسم کے آخر میں پہلے سے ہی یاء ہے۔ اور وہ یاء ایسی ہے کہ جس کا ماقبل مقصور ہے۔ اور ہم اس یاء والے اسم کو پھر مضاف کرنا چاہتے ہیں یاء متکلم کی طرف، کہ وہ ایک ایسا اسم ہے کہ پہلے سے ہی اس کے آخر میں یاء ہے یعنی "إِنْ كَانَ آخِرُ الِاسْمِ يَاءً" کہ پہلے سے ہی اس اسم کے آخر میں یاء ہے۔ "مَقْصُورًا مَا قَبْلَهَا" اور اس یاء کا ماقبل مقصور ہے۔ اور اب ہم اس کو اضافت دینا چاہتے ہیں ایک اور یاء یعنی یائے متکلم کی طرف۔ مثال: جیسے قاضی۔ اب قاضی کے آخر میں یاء ہے، یاء کا ماقبل مقصور ہے قا ضی۔ اب ہم اس کو مضاف کرنا چاہتے ہیں یاء متکلم کی طرف۔ اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں: کوئی مشکل نہیں، دو یاء اکٹھی ہو جائیں گی ، "أَدْغَمْتَ الْيَاءَ فِي الْيَاءِ"، باب مضارع کا قانون، یہاں پہلی یاء کو دوسری یاء میں یعنی قاضی والی یاء کو یاء متکلم میں ادغام کر دیں گے "وَفَتَحْتَ الْيَاءَ الثَّانِيَةَ" اور دوسری یاء کو فتحہ دے دیں گے، کیوں؟ تاکہ دو ساکن اکٹھے نہ ہو جائیں۔ لہٰذا آپ قاضی کو جب یاء متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو آپ کہیں گے قاضیَّ اس یاء کو دوسری یاء میں ادغام کر دیا۔
اسمِ صحیح یا جاری مجریٰ صحیح کو مضاف کیا تھا تو اس کا حکم بھی گزر گیا۔ اب ایسا اسم جس کے آخر میں یاء اور ماقبل مقصور ہو اگر اس کو مضاف کرنا ہے یاء متکلم کی طرف تو اس کا حکم بھی گزر گیا۔ اب تیسرا: اگر ایک ایسا اسم ہے کہ جس کے آخر میں واو ہے اور واو کا ماقبل مضموم ہے۔ اور ہم اس کو مضاف کرنا چاہتے ہیں یاء متکلم کی طرف، ایک اسم ہے جس کے آخر میں واو اور ایسی واو کہ جس کا ماقبل مضموم ہے۔ ہم اس اسم کو مضاف کرنا چاہتے ہیں یاء متکلم کی طرف۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں: اس واو کو یاء میں تبدیل کریں گے، پھر اس یاء کو یاء متکلم جو دوسری یاء ہے اس میں ادغام کریں گے اور اس دوسری یاء کو پھر فتحہ دیں گے۔ مثال بڑی واضح ہے، لفظ ہے مسلمون، ہم اس مسلمون کو یاء متکلم کی طرف مضاف کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں: جونہی آپ اس کو مضاف کریں گے تو نون اضافت کی وجہ سے گر جائے گی۔ پھر بن جائے گا مسلموی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمو جو اسم ہے، آگے تو یاء متکلم آ گئی ، آخر میں واو ہے اور واو کا ماقبل بھی مضموم ہے، جب مضموم ہے تو ہم اس واو کو یاء میں تبدیل کریں گے۔ پھر اس یاء کو یائے متکلم میں ادغام کریں گے۔ یہ بن جائے گا مسلمیّ۔ پھر اس یاء متکلم کو اضافت دیں گے تاکہ دو یاء ساکن اکٹھی نہ ہو جائیں۔ وہ بن جائے گا مسلمیّہ۔ پھر یاء کی مناسبت کے لیے مسلم کی میم کو کسرہ دیں گے تو یہ بن جائے گا مسلمیَّ۔ یہ تین قسم کے اسماء تھے کہ اگر کسی اسم کو ہم یاء متکلم کی طرف مضاف کرنا چاہتے ہیں ان اسماء میں سے کسی اسم کو تو اس کی اضافت کا حکم،اورطریقہ کار کیا ہوگا۔
اس کے بعد آگے یہ بحث پھر علیحدہ ہے۔ پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے پاس کچھ اسماء ہیں۔ جن کو ہم کہتے ہیں اسمء ستہ۔ اخ ایک، اب دو، حم تین، هن چار، فم پانچ، اور ذو چھ۔ ان کو کہا جاتا ہے اسماء ستہ مکبرہ ۔
اسماء ستہ مکبرہ کی یاءمتکلم کی طرف اضافت
یہ ہیں چھ اسماء۔ ان میں سے اگر آپ کسی ایک کو یاء متکلم کی طرف مضاف کرنا چاہتے ہیں تو کیسے مضاف ہوں گے؟ جواب: ان اسماء میں سے جو ذو ہے وہ تو ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ذو ہمیشہ مضاف ہوتا ہے البتہ اسم ظاہر کی طرف۔ وہ ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔ جو باقی ہیں وہ البتہ ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔
"وَفِی الْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ" وہ جو اسمائے ستہ مکبرہ جو مشہور ہیں اب، اخ، حم، هن، فم اور ذو۔ فرماتے ہیں: "وَفِی الْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ مُضَافَةً إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ"۔ وہ اسماء ستہ جب وہ مضاف ہو رہے ہوں یاء متکلم کی طرف، یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا۔ یا یوں کہیں، اگر آپ اسماء ستہ کو یاء متکلم کی طرف مضاف کرنا چاہتے ہیں "تَقُولُ" تو آپ کہیں گے: اخی، ابی، حمی، هنی، وفی۔ اکثر کہتے ہیں کہ فم کو فی پڑھا جائے اور بعض کہتے ہیں نہیں فم کو فمی پڑھا جائے یعنی اس کی میم کو بھی برقرار رکھا جائے، "وَفَمِي عِندَ قَوْمٍ" بعض لوگ کہتے ہیں کہ فم کو فمی ہی پڑھا جائے فی نہ پڑھا جائے۔ خوب یہ تو ہو گئے پانچ۔
چھٹا ذو کا کیا ہوگا؟ جواب۔ "ذُو لَا يُضَافُ إِلَى مُضْمَرٍ أَصْلًا"۔ ذو ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔ ذو ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے اور اس کا مضاف الیہ بھی اسم ظاہر ہوتا ہے۔ ان شاء الله اس کی بحث بعد میں آئے گی۔ یعنی اسماء ستہ میں سے ذو ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا ،بالکل نہیں ہوتا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔
اب یہاں سوال مقدر ہے اگلا اس کا جواب ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جناب ہم آپ کو شاعر کا ایک شعر دکھاتے ہیں کہ اس نے اپنے شعر میں ذو کو ضمیر کی طرف مضاف کیا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ذو اصلا ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا؟ فرماتے ہیں: کہنے والے کا یہ قول کہ جناب میں دکھاتا ہوں آپ کو، کیا دکھاتا ہوں؟ کہ ذو ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ کیوں؟ شاعر نے کہا ہے: "إِنَّمَا يَعْرِفُ ذَا الْفَضْلِ مِنَ النَّاسِ ذَوُوهُ"۔ اب اس میں دیکھو ذو کو هُ ضمیر کی طرف مضاف کر کے استعمال کیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں "قَوْلُ الْقَائِلِ شَاذٌّ"۔ یہ قول شاذ ہے، نادر ہے۔ یہ ضرورت شعری کے لیے اس نے ایسا کیا ہو گا وگرنہ علی القاعدہ ذو ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔
آگے فرماتے ہیں۔ "وَإِذَا قَطَعْتَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ عَنِ الْإِضَافَةِ" اگر آپ ان اسماء ستہ کو بغیر اضافت کے پڑھتے ہیں یعنی ان کو اضافت کے ساتھ نہ پڑھیں، مضاف بنا کر ان کو نہ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے اخٌ، ابٌ، حمٌ، هنٌ، فمٌ۔ لیکن ذو "لَا يُقْطَعُ عَنِ الْإِضَافَةِ"۔ ذو کبھی بھی بغیر اضافت کے نہیں ہوتا یعنی ذو اضافت سے قطع نہیں ہو سکتا۔ ذو ہمیشہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتا ہے۔
"هَذَا كُلُّهُ بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الْجَرِّ"۔ یہ تو ساری اضافت معنوی کی باتیں تھیں کہ جہاں حرف جر مقدر ہوتا ہے۔لیکن جہاں حرف جر لفظا ذکر ہو گا اس کی بات ان شاء الله ہم قسم ثالث جب حروف میں جائیں گے تو وہاں مکمل کریں گے۔
وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ