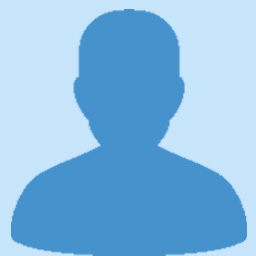"امر مخاطب را از فعل مستقبل مخاطب گیرند"
فعل امر حاضر معلوم کو فعل مضارع حاضر معلوم سے بناتے ہیں، یعنی آپ یوں کہیں گے کہ فعل امر مخاطب، فعل مضارع(مستقبل) کے چھ صیغوں سے بنتا ہے۔
و طريقه آن، آن است كه حرف مستقبل را كه تاء است ، از اوّل وى بيندازند"
اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف مستقبل (یعنی علامتِ مضارع) جیسے تَضرِبُ، تَنصُرُ اور تَعلَمُ وغیرہ میں تاء ہے، اس کے شروع سے حذف کردیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں:
"اگر مابعد حرف مضارع متحرّك باشد ،احتياج به همزه نباشدو به همان حركت امر بنا كنند و حركت آخر ونون عوض رفع بيفتد به وقفى"
اگر تائے مضارع کے بعد والا حرف متحرک ہے یعنی اس پر کوئی زبر ،زیر یا پیش پہلے سے موجود ہے تو ہمزہ ابتدا میں لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ فعل امر اسی حرکت سے بناتے ہیں اور نون عوض رفع (یعنی نونِ اعرابی) وقف کی وجہ سے گر جائے گی جیسے تُصَرِّفُ سے صَرِّفْ بن جائے گا ۔باب تفعیل میں فعل مضارع حاضر کی گردان اس طرح کرتے تھے : تُصَرِّفُ، تُصَرِّفَانِ، تُصَرِّفُونَ، ان صیغوں سے جب تاء کو گرادیا اور آخر کو ساکن کردیا جائے تو بنے گا: صَرِّفْ، صَرِّفَا، صَرِّفُوا۔ وہ جو تثنیہ میں نون تھی وہ بھی گر جائے گی وقف کی وجہ سے اور تُصَرِّونَ میں جو نون تھی وہ بھی گر جائے گی۔
"پس در باب تفعيل ، امر مخاطب بر اين وجه باشد"
پس باب تفعیل میں امر مخاطب اس طرح سے ہوگا: صَرِّفْ، صَرِّفَا، صَرِّفُوا، صَرِّفِي، صَرِّفَا، صَرِّفْن؛ اس لیے کہ صَرِّفْ اصل میں تُصَرِّفُ تھا، اس سے علامتِ مضارع ( تاء) کو گرادیتے ہیں اور امر کی وجہ سے آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں لہٰذا اس طرح صَرِّفْ بن جاتا ہے ۔
صَرِّفَااصل میں تُصَرِّفَانِ تھا جب تاء کو ہٹا دیا تو یہ بن گیا صَرِّفَانِ لیکن نون جوعوض رفع والی تھی وہ بھی اس وقف کی وجہ سے گر گئی تو یہ بن گیا صَرِّفَا تثنیہ کا صیغہ ۔
وہاں پڑھتے تھے تُصَرِّفُونَ (جمع مذکر حاضر )اب اس کی تاء کو ہم یہاں گرا دیں گے تو یہ بنے گا صَرِّفُونَ اور نون وقف کی وجہ سے ساقط ہوجائے گی کیونکہ وہ نون اعرابی ہےلہٰذا صَرِّفُوا بن جائے گا۔
صَرِّفْ، صَرِّفَا، صَرِّفُوا، فعل امر حاضر معلوم کے یہ تینوں صیغے مذکّر کے ہیں۔
صَرِّفِي، صَرِّفَا، صَرِّفْنَ، فعل امر حاضر معلوم کے یہ تینوں صیغےمؤنّث کے ہیں۔
فعل مضارع معلوم میں مؤنّث کے ان تینوں صیغوں کی گردان اس طرح تھی: تُصَرِّفِينَ، تُصَرِّفْانَ، تُصَرِّفْنَ۔
اب سوال یہ ہے کہ تُصَرِّفِينَ سے صَرِّفِي کیسے بنا؟
اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تُصَرِّفِينَ سے علامتِ مضارع تاء اور وقف کی وجہ سے نون کو گرادیاجائے تو صَرِّفِي بن جائے گا۔تثنیہ کا صیغہ (صَرِّفَا)بھی اسی طرح بنے گا ۔
صَرِّفْنَ اصل میں تُصَرِّفنَ تھا، اس سے فقط تاء کو حذف کریں گے البتہ یاد رہے کہ حرف نون باقی رہے گا، اسے حذف نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ یہ نون جمع کی علامت ہے اور علامت کو کبھی حذف نہیں کیا جاتالہٰذا صَرِّفْنَ بن جائے گا۔
باب مفاعَلہ میں مخاطب کے صیغے یہ ہیں: تُضَارِبُ، تُضَارِبَانِ، تُضَارِبُونَ، تُضَارِبِينَ، تُضَارِبَانِ، تُضَارِبْنَ ۔
جب فعل امر بناتے ہوئے ہم تاء کو ہٹاتے ہیں تو اس کے بعد (ضاد) پہلے سے ہی متحرک ہے لہٰذا ہمیں ہمزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی ترتیب وہی ہوگی جو صَرِّفْ میں تھی۔
اسی طرح رباعی مجرد میں کیا تھا دَحرَجَ یُدَحرِجُ میں مستقبل کے مخاطب کے صیغے میں کیا تھا؟
تُدَحرِجُ، تُدَحرِجَانِ، تُدَحرِجُونَ، تُدَحرِجِينَ، تُدَحرِجَانِ، تُدَحرِجْنَ، اب یہاں پر کیا کریں گے؟
وہاں جب ہم تاء حرف مضارع کو ہٹاتے ہیں تو دال پہلے سے ہی متحرک ہے لہٰذا ہمیں ہمزہ لگانے کی ضرورت نہیں اور آخر کو ساکن کر دیتے ہیں پس تُدَحرِجُ سے دَحرِجْ بن جائے گا : دَحرِجْ، دَحرِجَا، دَحرِجُوا، یہ تینوں مذکّر کے جبکہ دَحرِجِي، دَحرِجَا، دَحرِجْنَ مؤنّث کے صیغےہیں۔
مذکورہ صورت میں جب تائے مضارع کو گرایا تو اس کے بعدوالا حرف متحرک تھا لہٰذا ہمیں ہمزہ لانے کی ضرورت نہیں تھی۔
"و اگر ما بعد حرف استقبال ساكن باشد"
اگر ہم فعل مضارع کے شروع سے حرف استقبال (تاء) کو ہٹا لیتے ہیں اوراس کے بعد جو حرف اصلی ہے وہ ساکن ہو یعنی اس پر کوئی حرکت نہ ہو جیسے تَضرِبُ میں(ضاد) ساکن ہے ، تَعلَمُ میں(عین) ساکن ہے، تَنصُرُ میں(نون) ساکن ہے۔ اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں:
"احتياج به همزه وصل افتد"
یعنی اس صورت میں ہمیں شروع میں ایک ہمزہ ٔوصل اضافہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
"و اگر مابعد آن ساكن ضمّه باشد همزه را مضموم گردانند"
اگر اس حرف ساکن کے بعد والا حرف مضموم ہو جیسے تَنصُرُ میں تاء کو حذف کیا، اس کے بعد والا حرف نون ساکن ہے، اس نون کے بعد والا حرف مضموم ہے تو ہمزہ کو بھی مضموم کردیتے ہیں۔
"و حركت آخر و نون عوض رفع را به وقفى بيندازند چون : اُنْصُرْ اُنْصُرٰا اُنْصُروا اُنْصُرى اُنْصُرٰا اُنْصُرْنَ"
آخر کی حرکت اور رفع کے بدل نون کو وقف کی وجہ سے گرادیتے ہیں اور اس طرح فعل امر حاضر معلوم کے چھ صیغے حاصل ہوتے ہیں: اُنْصُرْ، اُنْصُرٰا، اُنْصُروا، اُنْصُرى، اُنْصُرٰا، اُنْصُرْنَ۔
"و اگر ما بعد حرف ساكن فتحه باشد يا كسره همزه را مكسور گردانند"
اگر اس ساکن کے بعد والے حرف پر فتحہ یا کسرہ ہو توہمزہ کو مکسور کردیتے ہیں جیسے تَعلَمُ کے لام پر فتحہ ہے ، تَضرِبُ کی راء مکسور ہے، اس صورت میں ہمزہ کو مکسور کردیتے ہیں اور آخر پر ویسے ہی وقف آجائے گا تو پس اصل میں تھا: تَعْلَمُ، تَعْلَمَانِ، تَعْلَمُونَ، تَعْلَمِينَ، تَعْلَمَانِ، تَعْلَمْنَ اور فعل مضارع کے ان صیغوں سے فعل امر حاضر معلوم کے یہ چھ صیغے حاصل ہوں گے: اِعْلَمْ، اِعْلَمَا، اِعْلَمُوا، اِعْلَمِي، اِعْلَمَا، اِعْلَمْنَ۔
فعل مضارع کے چھ صیغوں تَضرِبُ، تَضرِبانِ، تَضرِبُونَ ، تَضرِبِينَ، تَضرِبانِ، تَضرِبْنَ سے فعل امر حاضر معلوم کے یہ چھ صیغے حاصل ہوں گے:اِضْرِبْ، اِضْرِبٰا، اِضْرِبوا، اِضْرِبى، اِضْرِبا، اِضْرِبْنَ۔ اِضْرِبٰا اور اِضْرِبى میں موجود نون تثنیہ گر گئی چونکہ وہ رفع کے عوض میں تھی لیکن اِضْرِبْنَ کی نون برقرار ہے کیونکہ یہ جمع مؤنّث کی علامت ہے۔
فرماتے ہیں :
"و چون همزه وصل متصل شود به ما قبل خود ، ساقط گردد در لفظ و ثابت باشد در عبارت فَاطْلُبْ ثُمَّ اطْلُبْ"
یاد رہے کہ ہمزہ کی دو قسمیں ہیں:
۱۔ہمزۂ وصل
۲۔ہمزۂ قطع
اب سوال یہ ہے کہ ان دو میں کیا فرق ہے؟
اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمزۂ قطعی حروف اصلی میں سے ہوتا ہے جو کبھی ساقط نہیں ہوتا جبکہ ہمزۂ وصل اگر اس جملے یالفظ کو پچھلے جملے سے ملا دیا جائے تو پھر یہ ہمزہ وصل لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔
مثال: اِعْلَمْ، اس مثال میں ہمزہ پڑھا جا رہا ہے، اگر ہم اسی مثال میں ہمزہ سے پہلے ایک واو لگا دیں جیسے وَاعْلَمْ تو پھر یہی ہمزہ لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔
دوسری مثال: اِضْرِبْ،اس مثال میں ہمزہ پڑھا جائے گا، اگر ہم اسی مثال میں ہمزہ سے پہلے ایک واو لگا دیں جیسے وَاضْرِبْ تو پھر ہمزہ لکھنے میں آئے گالیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔
مصنف ایک قانون بتا رہے ہیں کہ اگر ہمزہ ٔوصل اپنے ماقبل کے ساتھ متصل ہو جیسے ہم کہتے ہیں: بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ، بسم اصل میں اسم ہے لیکن جب شروع میں باء آگئی تو اب ہمزہ نہیں پڑھتے۔
یاد رہے کہ اس مثال میں ہمزہ کتابت میں کثرتِ استعمال کی وجہ سے ساقط ہوا ہے۔
لہٰذا آپ یہ ایک قانون یاد کر لیں کہ ہر وہ لفظ جس کی ابتدا میں ہمزۂ وصل ہو، جب اس لفظ کواس سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملایا جائے گا تو وہ ہمزۂ وصل لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا جیسے فَاطْلُبْ (فاء) پہلے آگئی تو اب یہاں پر ہمزہ نہیں پڑھا جائے گا یا ثُمَّ اطْلُبْ میں پہلے ثمّ آ گیاہے تو اب ثُمَّ کے بعد ہمزہ نہیں پڑھا جا ئے گا۔