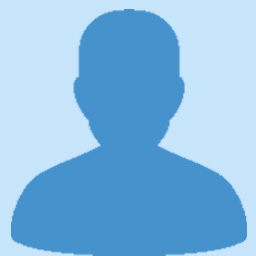شيءٍ فزيدٌ منطلق ، فحذف الفعل والجار والمجرور حتى بقى : أمّا فزيدٌ منطلق ، ولمّا لم يناسب دخول الشرط على فاء الجزاء نقل الفاء إلى الجزء الثاني ، ووضعوا الجزء الأوّل بين أمّا والفاء عوضاً عن الفعل المحذوف ، ثمّ ذلك الجزء إنْ كان صالحاً للابتداء فهو مبتدأ كما مرّ ، وإلّا فعامله ما بعد الفاء نحو : أمّا يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ ، فمنطلقٌ عامل في يوم الجمعة على الظرفيّة.
فصل : حرف الردع
«كَلّا».
وضعت لزجر المتكلّم وردعه عمّا تكلّم به كقوله تعالى : «رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا» (١) أي لا تتكلّم بهذا فإنّه ليس كذلك. هذا في الخبر ، وقد يجيء بعد الأمر أيضاً كما إذا قيل لك : اضْربْ زَيْداً ، فقلت : كَلّا ، أي لا أفعل هذا قطّ.
وقد جاء بمعنى حقّاً كقوله تعالى : «كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ» (٢) ، وحينئذٍ يكون اسماً يبنى لكونه مشابهاً لكلّا حرفاً ، وقيل يكون حرفاً أيضاً بمعنى إنّ لكونه لتحقيق معنى الجملة.
فصل : التاء الساكنة
وهي تلحق الماضي لتدلّ على تأنيث ما اُسند إليه الفعل نحو : ضَرَبَتْ هِنْدٌ ، وعرفت مواضع وجوب إلحاقها. وإذا لقيها ساكن بعدها وجب تحريكها بالكسر لأنّ الساكن إذا حرّك حرّك بالكسر نحو : قَدْ
____________________________
|
(١) الفجر : ١٦ ـ ١٧. |
(٢) التكاثر : ٤. |