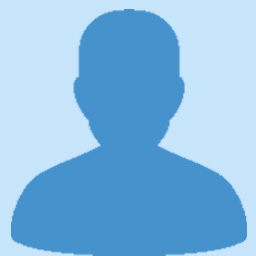فصل : حروف التنبيه
ثلاثة : «ألا ، وأما وها» ، وضعت لتنبيه المخاطب لئلّا يفوته شيء من الحكم.
«فألا وأما» لا تدخلان إلّا على الجملة ، اسميّة كانت نحو قوله تعالى : «أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ» (١) ، وكقوله :
|
أما وَالَّذي أبْكىٰ وَأضْحَكَ وَالَّذي |
|
أماتَ وأَحيىٰ وَالَّذي أمْرُهُ الْأمْرُ (٢) |
أو فعليّة نحو : ألا لا تَفْعَلْ ، وأما لا تَضْربْ.
الثالث : ها ، تدخل على الجملة نحو : ها زَيْدٌ قائِمٌ ، والمفرد نحو : هذا وَهؤُلاءِ.
فصل : حروف النداء
حروف النداء خمسة : «يا ، وأيا ، وهَيا ، وأي ، والْهَمْزَةُ المفتوحة للقريب» ، وأيا وهَيا للبعيد ، ويا لهما وللمتوسّط ، وقد مرّ احكامها.
فصل : حروف الإيجاب
ستّة : «نَعَمْ ، وبَلْ ، وإيْ ، وأجَلْ ، وجَيْرِ ، وإنَّ».
____________________________
(١) البقرة : ١٢.
(٢) يعنى : آگاه باش قسم به آنچنان كسى كه گريانيده است و خندانيده است خلايق را و قسم به آنچنان كسى كه ميرانيده و زنده گردانيده است خلايق را و قسم به آنچنان كسى كه حكم او ثابت و محقق است و لا محاله جارى خواهد شد. شاهد در اما استفتاحيّه است كه بمعنى الا است و از براى تنبيه است و واقع شده است پيش از واو قسم و داخل شده است بر جمله اسميّة. (جامع الشواهد).