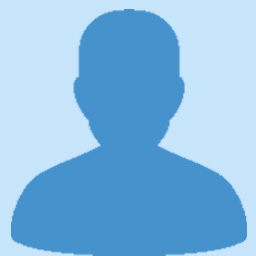النوع الثاني
الحُروفُ المشبّهةُ بِالفَعلِ، وَهَيِ َتدخُلُ عَلى المبتدأِ والخَبرِ، تَنصِبُ المبتدأَ وتَرفَعُ الَخبرَ، وَهِيَ سِتّةُ حُروفِِ
ہم کتاب پڑہ رہے ہیں شرح ماۃ عامل سو عامل جو عبد القاھر جرجانی مرحوم نے جمع کیئے تھے ان کی شرح پھر ان میں سے کچھ عوامل لفظیہ تھے کچھ معنویہ فالحال ھم عوامل لفظیہ کو پڑہ رہے ہیں ، نوع اول میں حروف جارہ کی بحث ہم نے پڑہی یہ حروف عامل ہیں یہ اسم کو جر دینے کا عمل کرتے ہیں ،
نوع ثانی بھی حروف کے بارے میں ہے ان کا نام ہے وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں ۔ یعنی حروف مشبہ بالفعل ، ہیں حروف لیکن عمل میں مشابھت رکھتے ہیں فعل کی ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ معنی کے لحاظ سے مثلا اِنَّ ، حَقَّقتُ کی معنی کو متضمن ہوتا ہے یعنی ان میں معنی فعل والا ہوتا ہے جیسے کَاَنَّ ، شَبَّهتُ اب اس میں تَشَبّہ کی معنی پائی جاتی ہے جو یقیناََ وہ فعل ہے ، تو ایک شباھت ان میں یہ ہے دوسری شباھت جیسے فعل فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے یہ حروف بھی اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں ، یعنی یہ حروف بھی دو چیزوں میں عمل کرتے ہیں ایک کو زبر دیتے ہیں ایک کو پیش جیسے ضَربَ زیدٌ عمرواََ تو اسی وجہ سے ان کو حروف مشبہ بالفعل کھا جاتا ہے یعنی وہ حروف جو مشابہ ہیں فعل کے ۔
یہ حروف مشبہ بالفعل کیا کرتے ہیں ؟ فرماتے ہیں کہ
1- مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں گویا یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں ۔
2- مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں ، اگر یہ حروف نہ ہوتے تو وہ مبتدا تھی اب یہ مبتدا انہی کا اسم بن جائے گا اور خبر ان کی خبر مثال : زَيْدٌ قائمٌ ، یہ جملہ اسمیہ ہے زید مبتدا ہے قائم اس کی خبر لیکن اسی مبتدا اور خبر پر ان حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی حرف آجائے تو زیدٌ قائمٌ سے یہ جملہ إنَّ زَيْداً قائمٌ ہو جائے گا ، زید ان کا اسم ہے اور قائم ان کی خبر ہے ،
3- وہ مبتدا ان حروف کا اسم اور خبر انہی حروف کی خبر بن جائے گی ۔
* حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں : اِنَّ اَنَّ کَاَنَّ لَیتَ لٰکِنَّ لَعَلَّ
اب ذرا غور کرنا ہے کہ جہاں تک ہے عمل، وہ تو یہ چھے کے چھے ایک ہی عمل کرتے ہیں کہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں ۔ مبتدا کو نصب دیتے ہیں، پھر وہ بن جاتا ہے ان کا اسم، اور خبر کو دیتے ہیں رفع، وہ بھی ان کی خبر۔ اب مسئلہ جو آگے یاد کرنے والے نکات ہیں،
بہت توجہ فرمانی ہیں، وہ کیا؟
1: اِنَّ اور اَنَّ کہاں پر پڑھنا ہے اور اِنَّ کہاں پر پڑھنا ہے؟ یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے، اور اس کو یاد بھی کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کئی مقام ایسے ہیں جہاں اِنَّ پڑھنا ہے، اَنَّ درست نہیں ہوگا، اور کہیں پر اَنَّ پڑھنا ہے، اِنَّ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے بھی، لَیْتَ اور لَعَلَّ دونوں "کاش" کے معنی میں ہیں، اردو میں ، لیکن دیکھیں گے ان میں بھی ایک خاص فرق ہے۔ ہم ان شاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کو آسانی سے بتاتے ہیں۔
النوع الثاني : الحُروفُ المشبّهةُ بِالفَعلِ،
وہ حروف جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، وَھِیَ تَدخُلُ عَلی المُبتَدَاِ وَ الخَبَرِ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر۔ تَنصِبُ المُبتَداَ (مبتدا کو نصب دیتے ہیں)، وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ (اور خبر کو رفع دیتے ہیں)۔ وَهِيَ سِتَّةُ حُرُوفٍ (اور یہ چھے حروف ہیں)۔ یہ ہو گیا ان کا اَثَر۔ کون کون سے ہیں چھے؟ جی، آگے انہوں نے خود لکھا: إِنَّ، أَنَّ، كَأَنَّ، لَيْتَ، لَكِنَّ، لَعَلَّ۔ ٹھیک ہو گیا ۔
اب یہ چھے اس بات میں تو یہ مشترک ہیں کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں، وہ پھر ان کا اسم بن جاتی ہے، اور اگلی ان کی خبر۔ اب ہر ایک کے معنی کیا دیتا ہے؟ إِنَّ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ أَنَّ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ آخر اس عمل جو اعراب کا دیتے ہیں، رفع اور نصب، اس سے ہٹ کر کوئی ان کا معنی بھی تو ہوگا کہ کہاں کیا کرتے ہیں؟
فرماتے ہیں: إِنَّ وَأَنَّ (یہ جو پہلے دو ہیں، إِنَّ اور أَنَّ)۔ إِنَّ اور أَنَّ اسم یعنی وہ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع، یہ عمل میں تو ہو گیا برابر۔ معنی کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں: ان کا معنی یہ ہے: "هُمَا لِتَحْقِيقِ مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ" (إِنَّ اور أَنَّ جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے آتے ہیں)۔ کیا مطلب؟ جملہ تھا زیدٌ قائمٌ جملہ اسمیہ ہت اب اس کا مضمون یہ ہے نا کہ زید کھڑا ہے۔ مضمون جملہ یہ ہے نا کہ زید کا قیام، زید کھڑا ہے۔ لیکن جب اس پر إِنَّ آ گیا: "إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ"، اب اس کا ترجمہ یہ نہیں کرنا کہ زید کھڑا ہے۔ اب کریں گے: "تَحْقِيق کہ زَيْد قَائِم ہے" (یہ نہیں، یہ جملہ ہے اسمیہ کا زید قائم جو مضمون تھا، زید کا قیام، زید کا کھڑا ہونا، یہ اس کی تحقیق کرتا ہے)۔
یعنی، اگر متکلم کہتا ہے: "إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ"، تو گویا کہ وہ کہہ رہا ہے: "حَقَّقْتُ قِيَامَ زَيْدٍ" (میں نے زید کے قیام کی تحقیق کی ہے)۔ "حَقَّقْتُ" یہ فعل ہو گیا، "قِيَامَ زَيْدٍ" مفعول ہے۔ مفعول ہو گیا کیا؟ کہ میں نے قیام زید کی تحقیق کی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ جس کو ہم کہتے ہیں کنفرم کی ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ لیکن جب إِنَّ آئے گا، تو اب ترجمہ کریں گے: "إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ" کا معنی ہوگا: "تحقیق کہ زید کھڑا ہے"، "حَقَّقْتُ" (میں نے تحقیق محقق کی ہے، میں نے کنفرم کی ہے کس کو؟ قِيَامَ زَيْدٍ، زید کے قیام کو)۔ یعنی یہ بات ایسی نہیں ہے، میں نے اس کی تحقیق کی ہے، زید کے قیام کی۔
اسی طرح: "وَبَلَغَنِي" (مجھے پتہ چلا ہے) "أَنَّ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ" (أَنَّ زَيْدًا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تحقیق کے زید مُنْطَلِقٌ، چلنے والے ہیں، جانے والے ہیں)۔ اب ذرا غور کریں: یعنی اصل میں جملہ کیا تھا؟ "زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ" (زید چلنے والے ہیں)۔ "انطلاق" چلنا۔ لیکن جب اس پر أَنَّ آ گیا، تو أَنَّ کے بعد اب نہیں کہنا کہ زید چلنے والے ہیں۔ آپ ترجمہ کریں گے کہ : تحقیق، یعنی "بَلَغَنِي" (مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کیا؟ کہ أَنَّ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ، تحقیق کے زید جانے والے ہیں) کیا مطلب؟ یعنی أَنَّ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ کا مطلب ہم کریں گے: "بَلَغَنِي" (مجھے یہ بات پہنچی ہے، مجھے اس بات کا علم ہے کیا بات پہنچی ہے؟ کہ ثُبُوتُ اِنطِلاقِ زَیدِِ، زید کے چلنے کا، جانے کے ثبوت کی)۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ اُس کا چلا جانا ثابت ہے، مجھے اس بات کی اطلاع پہنچی ہے۔