يكون ما بعدها داخلاً في ما قبلها إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها، نحو قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، وقد لا يكون ما بعدها داخلاً في ما قبلها إن لم يكن ما بعدها من جنس ما قبلها، نحو قوله تعالى: ﴿ثم أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وحتّى لانتهاء الغاية في الزمان، نحو: «نمت البارحة حتى الصباح» وفي المكان، نحو: «سرت البلد حتّى السوق»، وللمصاحبة، نحو: «قرأت وردي حتى الدعاء» أي: مع الدعاء، وما بعدها قد يكون داخلاً في حكم ما قبلها نحو: «أكلت السمكة حتى رأسها»، وقد لا يكون داخلاً فيه، نحو المثال المذكور، وهي مختصّة بالاسم الظاهر بخلاف «إلى» فلا يقال: «حتّاه» ويقال: «إليه». وعلى للاستعلاء، نحو: «زيد على السطح» و«عليه دين»، وقد تكون بمعنى الباء نحو: «مررت عليه» بمعني «مررت به»، وقد تكون بمعنى في، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [البقرة: ۲۸۳]، أي، في سفر. وعن للبعد والمجاوَزة، نحو: «رميت السهم عن القوس». وفي للظرفية، نحو: «المال في الكيس» و «نظرت في الكتاب»، وللاستعلاء، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي
درس شرح مائة عامل
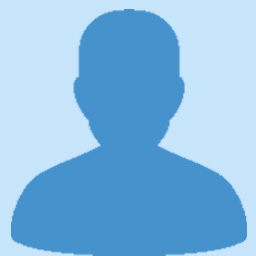
خطبہ
حَتَّى حرف جر کے معانی
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حَتَّى لِاِنتِھاءِ الغَايَةِ فِی الزَّمَانِ نحو: نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ او فی المکان: بحث ہماری چل رہی تھی حروف جارہ کی وہ حروف جو اسم پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل ہونے کے بعد اس اسم کو جر دیتے ہیں۔ ان حروف میں سے ایک حرف ہے "حَتَّى"۔ حَتَّى کیا عمل کرتا ہے؟ اسم کو جر دیتا ہے۔ لیکن یہ "حَتَّى" کبھی انتہاء غایت فی الزمان میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی انتہاء غایت فی المکان میں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہو اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے یہ کام کس وقت تک کیا، یعنی جب وہ وقت آیا، میں نے یہ کام ختم کر دیا، اس کو کہتے ہیں انتہاء غایت فی الزمان اور اگر شخص کوئی کام کر رہا ہو اور پھر وہ بتائے کہ یہ کام میں نے کس جگہ تک کیا، یعنی جب وہاں پہنچا، پھر میں نے یہ عمل ختم کر دیا، اس کو کہتے ہیں انتہاء غایت فی المکان ۔ یہ "حَتَّى" انتہاء غایت فی الزمان کو بھی بیان کرتا ہے اور انتہاء غایت فی المکان کو بھی بیان کرتا ہے۔
انہوں نے جو مثالیں دی ہیں:
زمان کی مثال: نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ ۔
"نِمْتُ" (میں سویا) واحد متکلم ہے۔
"الْبَارِحَةَ" گزشتہ رات کو کہتے ہیں، یعنی جو رات گزر جائے۔
ایک شخص کہتا ہے: "نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ" (میں گزشتہ رات صبح تک سویا)۔ یعنی کیا؟ وہ جو سونے کا عمل انجام دے رہا تھا، وہ گزشتہ رات چلتا رہا حَتَّى الصَّبَاحِ (صبح تک)۔ جب صبح ہوئی، پھر میں اٹھ گیا۔ یعنی یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو دس گیارہ بجے اٹھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: جب صبح ہوئی، بس میں اٹھ گیا۔ یقیناً نماز پڑھی ہوگی۔
مکان کی مثال: سِرْتُ الْبَلَدَةَ حَتَّى السُّوقِ ۔
"سِرْتُ" (میں چلا) واحد متکلم ہے۔
"الْبَلَدَةَ" شہر کو کہتے ہیں۔
ایک شخص کہتا ہے: "سِرْتُ الْبَلَدَةَ حَتَّى السُّوقِ" (میں شہر میں بازار تک چلتا رہا)۔ یعنی جب بازار آیا، میں رک گیا۔ پھر میں ادھر ادھر رہا، بازار میں نہیں گیا۔ یعنی کیا؟ میرے چلنے کے انتہا کا جو مقام تھا، جہاں میرا چلنا ختم ہو گیا، وہ تھا بازار۔
خوب! پس گویا "حَتَّى" کا عمل کیا کرتا تھا؟ اس کو ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے کہ عمل تو یہ کرتا تھا کہ اسم کو جر دیتا تھا، لیکن جن معانی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اس سے جو معنی لینا ہے، کبھی یہ انتہاء غایت فی الزمان کا معنی دیتا ہے، کبھی یہ انتہاء غایت فی المکان کا معنی دیتا ہے۔
اور آگے فرماتے ہیں کہ کبھی یہ مصاحبت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ میں کئی دفعہ گذارش کر رہا ہوں، مصاحبت کا اردو میں ترجمہ ہم "ساتھ" کرتے ہیں۔ عربی میں "مَعَ" ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ کبھی کبھی "حَتَّى" بمعنی "مَعَ" کے استعمال ہوتا ہے، یعنی "حَتَّى" ساتھ کا معنی دیتا ہے، تو بھی یہ درست ہے۔ ٹھیک ہے جی!
خوب! اب یہ جو مصاحبت ہے، اس کی پہلے بھی ایک مثال تھی، وہاں بھی گذارش کی تھی، آج دوبارہ بھی کرنی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ "حَتَّى" کا مابعد (جو کچھ "حَتَّى" کے بعد آتا ہے) "حَتَّى" کے ماقبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں میں نے مثال آپ کو دے دی تھی، ہم نے پیش کی تھی: "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ"۔ وہاں میں نے کہا تھا کہ الی کا مابعد (یعنی "الْمَرَافِقِ") الی کے ماقبل ("أَيْدِيَكُمْ") کے حکم میں شامل ہے۔ یہاں بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی "حَتَّى" کا مابعد "حَتَّى" کے ماقبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی "حَتَّى" کا مابعد "حَتَّى" کے ماقبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا۔
اگر اس کی کچھ مثالیں بھی ہیں، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تاکہ اس کے ساتھ آپ کو پھر مشکل نہ ہوں۔
"حَتَّى" حروف جارہ میں سے ایک ہے۔
"حَتَّى" کیا کرتا ہے؟ لِاِنتِھاءِ لِلغَايِۃِ (غایت کو بیان کرتا ہے)۔
یہ غایت کو، یعنی مقصد کے انتہا کو بیان کرتا ہے۔
فِی الزَّمَانِ (زمان کے لحاظ سے) بھی، میں نے آپ کو آسان اردو میں گزارش کیے، یعنی کبھی "حَتَّى" یہ بیان کرتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا تھا، یا کوئی بھی کر رہا تھا، اس کام کے کرنے کا وقت کب تھا، یعنی اس کے کام کی وقت کے لحاظ سے انتہاء بتاتا ہے کہ جب یہ وقت آیا، پھر وہ کام ختم ہو گیا۔
مثال:
نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ
"نِمْتُ" (میں سویا) واحد متکلم ہے۔
"الْبَارِحَةَ" گزشتہ رات کو کہتے ہیں۔
"حَتَّى الصَّبَاحِ" صبح تک۔
یہ "حَتَّى" کیا بیان کر رہا ہے؟ کہ وہ جو میں سو رہا تھا، میرے سونے کا عمل گزشتہ شب چلتا رہا، چلتا رہا، حَتَّى الصَّبَاحِ (صبح تک)۔ لیکن جب صبح ہوئی، تو یہ انتہاء غایت فی الزمان ہے۔ بس سونے کا جو انتہا تھی، اس عمل کا جو اختتام ہوا، صبح ہوتے ہی سونے کا کام ختم ہو گیا۔
اسی طرح فی المکان:
سِرْتُ الْبَلَدَةَ حَتَّى السُّوقِ
"سِرْتُ" (میں چلا) واحد متکلم ہے۔
"الْبَلَدَةَ" شہر کو کہتے ہیں۔
"حَتَّى السُّوقِ" بازار تلک۔
یہ کیا بیان کر رہا ہے؟ کہ میں شہر میں چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، حَتَّى السُّوقِ (بازار تک)۔ یعنی کیا؟ جہاں سے بازار شروع ہوا، پھر میرے چلنے کا عمل وہاں پر ختم ہو گیا۔ اب یہ جگہ کے لحاظ سے انتہائے غایت بیان کر رہا ہے۔
فرماتے ہیں: وَلِلْمُصَاحَبَةِ (مصاحبت کے لیے بھی)۔ یہ "حَتَّى" مصاحبت کا معنی بھی دیتا ہے۔ مصاحبت کا معنی کئی بار گزارش کی ہے، اردو میں "ساتھ" ہوتا ہے یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی "حَتَّى" بمعنی "مَعَ" کے ہوتا ہے۔ عربی میں "مَعَ"، اردو میں "ساتھ"۔ مثال: قَرَأْتُ وِرْدِي حَتَّى الدُّعَاءِ
"قَرَأْتُ وَرْدِي" (میں نے اپنا ورد پڑھا)۔ "حَتَّى الدُّعَاءِ" دعا تک۔
یہاں "حَتَّى" کا معنی تلک نہیں کرنا، یہ نہیں کہ دعا شروع ہوتے ہی میں خاموش ہو گیا، بلکہ یہاں کرنا ہے: "قَرَأْتُ وِرْدِي" (میں نے اپنا ورد پڑھا)، پھر وہی جو روٹین میں انسان اپنے دعا و اذکار جو بھی پڑھتا ہے، وہ میں نے پڑھے "حَتَّى الدُّعَاءِ"۔ یہاں "حَتَّى" بمعنی "مَعَ" ہے، یعنی "حَتَّى الدُّعَاءِ" (دعا سمیت)۔ یعنی میں نے جو اپنے ورد اور اذکار پڑھنے تھے، وہ سارے پڑھے دعا کے ساتھ۔
آگے فرماتے ہیں:
وَمَا بَعْدَهُ قَدْ يَكُونُ دَاخِلًا فِي حُكْمِ مَا قَبْلَهُ۔ اور "مَا بَعْدَهُ" (جو کچھ "حَتَّى" کے بعد ہوتا ہے) "حَتَّى" کا مابعد ہے جیسے الدُّعَا، اَلسُّوقُ ، اَلصَّباح ، قَدْ يَكُونُ دَاخِلًا (کبھی کبھی یہ مابعد داخل ہوتا ہے) فِي حُكْمِ مَا قَبْلَهُ (اس حکم میں جو "حَتَّى" کے ماقبل کا ہے)۔
مثال دیتے ہیں، بہت واضح ہو جائے گا:
نَحْو: أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا
"أَكَلْتُ السَّمَكَةَ" (میں نے مچھلی کھائی)۔
"حَتَّى رَأْسِهَا" اس کے سر تک۔
یہاں "رَأْسِهَا" (اس کا سر) "حَتَّى" کے مابعد ہے، اور یہ "حَتَّى" کے ماقبل ("السَّمَكَةَ") کے حکم میں داخل ہے، یعنی میں نے مچھلی کو اس کے سر تک کھایا۔)
کیا مچھلی "حَتَّى رَأْسِهَا" کہتے ہیں؟ مچھلی "رَأْسِهَا" (اس کے سر) تک۔ اب یہاں اس کا معنی ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہ یہ "رَأْس" (سر) اُس "سَمَكَة" (مچھلی) کے حکم میں داخل ہے۔ مچھلی کا حکم کیا تھا؟ کھانا۔ "أَكَلْتُ" (میں نے کھایا)۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مچھلی جو کھائی "حَتَّى رَأْسِهَا" (اس کے سر تک)، میں تو اُس کا سر بھی ساتھ کھا گیا۔ اب یہ "رَأْس" (سر) اُس حکمِ "أَكَلْ" (کھانا) میں داخل ہے، جو حکمِ "أَكَلْ" اُس "سَمَكَة" (مچھلی) کے لیے تھا۔ یعنی گویا اس کا مطلب ہوگا کہ میں نے مچھلی کھائی "حَتَّى رَأْسِهَا" (اس کے سر سمیت)، یعنی فقط مچھلی نہیں بلکہ سر بھی ساتھ کھایا۔
وَقَدْ لَا يَكُونُ دَاخِلًا فِيهِ (اور کبھی کبھی "حَتَّى" کا مابعد "حَتَّى" کے ماقبل میں داخل نہیں ہوتا)۔ نَحْوُ الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ (جیسا کہ پچھلی مثال تھی): "نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ"۔ اب حکم کونسا تھا؟ "نِمْتُ" (میں سویا)۔ اب یہ سونے والا حکم فقط "الْبَارِحَةَ" (گزشتہ رات) کے لیے تھا۔ "حَتَّى الصَّبَاحِ" (صبح تک) جو "حَتَّى" کا مابعد ہے، "الصَّبَاحِ" (صبح) کے لیے یہ سونے والا حکم نہیں تھا۔ اب یہ پڑھ گئی۔ بس، آپ جب اس کو یاد کریں گے تو آپ یوں کہیں گے: کبھی کبھی "حَتَّى" کا مابعد "حَتَّى" کے ماقبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی "حَتَّى" کا مابعد "حَتَّى" کے ماقبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہوئی؟ یہ قصہ ختم۔
آگے فرماتے ہیں: اس "حَتَّى" کی ایک خصوصیت جو بیان کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ یہ "حَتَّى" اسمِ ظاھر کے ساتھ مختص ہے۔ یعنی "حَتَّى" کے بعد باقاعدہ اسم ہوتا ہے، ضمیر نہیں۔ جیسے "إِلَى" کو ہم کہہ سکتے ہیں إِلَیہ، "فِي" کو ہم کہہ سکتے ہیں فِيہ، "مِن" کے بعد کہہ سکتے ہیں مِنہُ، "با" کے ساتھ کہہ سکتے ہیں بِہ، لیکن "حَتَّى" یہ مختص ہے اسمِ ظاہر کے ساتھ۔ یعنی "حَتَّى" کے بعد ضمیر نہیں آئے گی۔
وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالِاسْمِ الظَّاهِرِ اور یہ "حَتَّى" مختص ہے بِالِاسْمِ الظَّاهِرِ اسمِ ظاہر کے ساتھ یعنی "حَتَّى" کے بعد ہمیشہ ایک اسم ہونا چاہیے، ضمیر نہیں۔ بِخِلَافِ إِلَى، جبکہ "إِلَى" کا حکم یہ نہیں ہے۔ "إِلَى" کے بعد اسم بھی ہو سکتا ہے، "إِلَى" کے بعد ضمیر بھی آ سکتی ہے، جیسے "إِلَيْهِ"، "إِلَيْهِمْ"، "إِلَيْهِمَا"، "إِلَيْكُمَا"۔ ہم نے دیکھا کہ ضمیر کی طرف وہ مضاف ہوتے رہتے ہیں۔
تو پس "حَتَّى" اور "إِلَى" میں ایک فرق: "حَتَّى" کے بعد ہمیشہ اسمِ ظاہر ہوگا، جبکہ "إِلَى" کے بعد ضروری نہیں ہمیشہ اسمِ ظاہر ہو، بلکہ ضمیر بھی آ سکتی ہے۔
لہٰذا آگے فرماتے ہیں: فَلَا يُقَالُ "حَتَّاهُ"، وَيُقَالُ "إِلَيْهِ"۔ لہٰذا "حَتَّاهُ" کہنا صحیح نہیں، لیکن "إِلَيْهِ" کہنا صحیح ہے۔ فَلَا يُقَالُ (نہیں کہا جائے گا) "حَتَّاهُ"، لیکن وَيُقَالُ (یہ مضارع مجہول ہے) "إِلَيْهِ"۔ جبکہ "إِلَيْهِ" کہنا، یعنی "إِلَى" کو ھِی ضمیر کی طرف مضاف کرنا جائز ہے۔ خوب! یہ دو تین باتیں تھیں جو "حَتَّى" سے مربوط تھیں۔
عَلَىٰ حرف جر کے معانی
خوب! اب اس کے بعد فرماتے ہیں: حروف جارہ میں سے ایک اور حرف وہ ہے "عَلَىٰ"۔ "عَلَى" ایک ہوتا ہے "إِلَى"، اور یہ ہوتا ہے "عَلَى"۔ "عَلَى" کیا کرتا ہے؟ عمل تو اس کا وہی ہے کہ یہ اسم کو جر دیتا ہے، لیکن اس کے معانی مختلف ہیں۔
لِلِاسْتِعْلَاءِ (بلندی کے لیے)۔ "اسْتِعْلَاء" کا لغوی معنی ہوتا ہے "بلندی"۔ جب کوئی چیز کسی سے بلند ہو، ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں "پر"۔ ٹھیک ہے؟ جیسے "عَلَى الْكُرْسِيِّ" (کرسی پر)، "عَلَى الْكِتَابِ" (کتاب پر)، "عَلَى رَأْسِي" (میرے سر پر)۔ یعنی ہم عام طور پر اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں "پر" کا۔ کیوں؟ کیونکہ "پر" ہم وہاں استعمال کرتے ہیں جو کسی چیز سے بلند ہو، جو اوپر ہو۔ اوپر والے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز فلاں پر پڑی ہے۔ اگر نیچے ہو تو نیچے کہیں گے۔ ہم اردو میں "پر" یہ استعمال کرتے ہیں: کتاب اگر فرض کرو اوپر پڑی ہے تو ہم کہتے ہیں "وہ کتاب ٹیبل پر پڑی ہے"۔ یہ تب کہیں گے جب وہ ٹیبل کے اوپر ہو۔ اگر وہ نیچے پڑی ہے تو ہم نہیں کہیں گے "کتاب ٹیبل پر پڑی ہے"۔ تو یہ "عَلَى" کا ایک معنی ہو جائے گا اردو میں "پر"۔ اور ویسے اس کے معنی کیا ہوں گے؟ "اسْتِعْلَاء" یعنی بلندی۔
اب یہ "اسْتِعْلَاء"، کبھی "اسْتِعْلَاء حقیقی " ہوتا ہے، اور کبھی "اسْتِعْلَاء مجازی" ہوتا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کبھی "الصاق" حقیقی تھا،جیسے بہ داءٌ اور کبھی "الصاق" مجازی تھا۔ یہ بھی اسی طرح ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت دو مثالیں دی ہیں:
"زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ" (زید چھت پر ہے)۔ یہاں "اسْتِعْلَاء" حقیقی ہے۔ کیسے؟ کہ چھت نیچے تھی، زید اس کے اوپر کھڑا تھا، واقعاً اس سے بلند تھا۔
"عَلَيْهِ دَيْنٌ" (اس پر قرض ہے)۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ نیچے کھڑا ہوتا ہے، اور قرض اس کے سر پر چڑھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کے ذمہ ہوتا ہے، تو یہاں مجازاً اس کو بھی بلندی کے معنی میں لیتے ہیں۔
خوب! فرماتے ہیں: "عَلَى" حروف جارہ میں سے ایک ہے۔ "عَلَى لِلِاسْتِعْلَاءِ ("عَلَى" بلندی کے لیے)۔ اردو میں اگر آپ یاد کر لیں تو آسان ہوگا، یعنی "عَلَى" کا حرفی معنی ہوگا "پر"۔ البتہ ہر جگہ نہیں، کہیں یہ مختلف معانی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بلندی کے لیے۔ پھر "اسْتِعْلَاء"۔ اب یہاں کتاب میں نہیں ہے، آپ نے خود اس کو مثالوں سے سمجھنا ہے کہ "اسْتِعْلَاء" حقیقی ہوگا، جیسے "زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ" (زید چھت پر ہے)۔ "سَطْح" کہتے ہیں چھت کو۔ اب یہ "اسْتِعْلَاء" حقیقی ہے، کہ واقعاً چھت نیچے تھی، زید اس کے اوپر کھڑا ہے۔ تو یہ ہو گیا بلندی حقیقی، "اسْتِعْلَاء" حقیقی۔
وَ "عَلَيْهِ دَيْنٌ" (اس پر قرض ہے)۔ اب یہ مثال ہے لیکن واقع میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ "اسْتِعْلَاء" حقیقی نہیں، بلکہ مجازی ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں "عَلَيْهِ دَيْنٌ" (اس پر قرض ہے)۔ اب ایسا نہیں ہوتا جیسے چھت کے اوپر بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ قرض میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نیچے کھڑا ہوتا ہے، قرض کوئی اس کے اوپر، اس کے سر پر ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ "اسْتِعْلَاء" یعنی اس کو "اسْتِعْلَاء" مجازی ہوتا ہے۔ گویا اس کے ذمہ ہے، اس پر ایک بوجھ ہے۔ تو اس معنی میں اس کو ہم "اسْتِعْلَاء" کہتے ہیں۔
آگے فرماتے ہیں:
وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى البَا (اور کبھی کبھی یہ "عَلَى" "با" کے معنی میں ہوتا ہے)۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ کئی حروف ایسے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں: یہ "عَلَى" کبھی کبھی "با" کے معنی میں ہوتا ہے۔ یعنی کیا؟ جیسے "بِا" الصاق کے لیے آتی تھی، یہ "عَلَى" بھی کبھی کبھی اسی "با" کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور "اسْتِعْلَاء" والا معنی نہیں، بلکہ اِلصاق کا معنی دیتا ہے۔ مثال: "مَرَرْتُ عَلَيْهِ" (میں اس کے پاس سے گزرا)۔ اب یہاں اگر "عَلَى" کا معنی "پر" والا کریں گے تو کیا مطلب ہے؟ "مَرَرْتُ عَلَيْهِ" (میں اس پر سے گزرا) کیا مطلب؟ یعنی وہ نیچے تھا، میں اس کے اوپر سے گزر گیا؟ حالانکہ یقیناً یہ مراد نہیں ہے۔ "مَرَرْتُ عَلَيْهِ" (میں اس کے پاس سے گزرا)۔)
"عَلَيْهِ" کا معنی ہے: "مَرَرْتُ بِهِ" (میں اس کے پاس سے گزرا)۔ یعنی "میں گُزرا اس کے قریب سے، اس کے ساتھ سے۔
تیسری بات:
"وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى فِي" (اور کبھی کبھی یہ "عَلَى" "فِي" کے معنی میں بھی ہوتا ہے)۔ "فِي" اردو میں کیا ہوتا ہے؟ "میں"یعنی ظرفیت، فرماتے ہیں، جیسے قرآنِ مجید میں ہے: "وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ"۔ اب یہاں "عَلَى" کا معنی "پر" نہیں کرنا کہ "اگر تم سفر پر ہو"، بلکہ "عَلَى" بمعنی "فِي" کے ہے۔ یعنی "وَإِنْ كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ" (اور اگر تم سفر میں ہو)۔ تو یہاں "عَلَى" بمعنی "فِي" کے ہے۔ بس "عَلَى" سے متعلق اتنا کہا۔
عَن حرف جر کے معانی
اس کے بعد فرماتے ہیں آگے حروف جارہ میں سے ایک اور حرف ہے "عَنْ" (عین اور نون)۔ "عَنْ" کا اردو میں حرفی معنی بنے گا "سے"۔ ٹھیک ہے جی؟ "مِن" کا بھی "سے" ہوتا ہے، "عَنْ" کا بھی "سے" ہوتا ہے، لیکن ان میں ذرا فرق ہوتا ہے۔ یہ "عَنْ" کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں: یہ "عَنْ" حروف جارہ میں سے ہے، جس اسم پر داخل ہوگا، اس کو جر دے گا۔ معنی کیا دیتا ہے؟ فرماتے ہیں: "عَنْ" معنی دیتا ہے "بُعد" اور "مُجَاوَزَہ"۔ "مجاوزہ" کیا ہے؟ یعنی کسی کا کسی چیز سے دور ہونا۔ ٹھیک ہے جی؟ کسی چیز سے دور ہونا، بُعدُ بعید کے معنی میں۔ آگے مثال لیں گے، بہت آسان ہے۔ یعنی اگر کوئی شیئ کسی سے دور ہو، کسی سے نکلے، کس سے تجاوز کرے، کس سے ہٹے، تو وہاں پر "عَنْ" کو لایا جاتا ہے۔
اچھا جی، مثال موجود ہے ہمارے پاس: "رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ" (میں نے تیر کمان سے چلایا)۔ "سَهْم" کہتے ہیں تیر کو، "قَوْس" کہتے ہیں کمان کو۔ اب یہاں "عَنْ" کیا بتا رہا ہے؟ بہت غور کریں۔ "عَنْ" بتا رہا ہے کہ میرا مابعد میرے ماقبل سے نکلا، میرا مابعد میرے ماقبل سے دور ہوا، میرا مابعد میرے ماقبل سے تجاوز کیا۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں: "رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ" (میں نے تیر کمان سے چلایا)۔ تو اب یہ سوال تو تھا نا کہ "چلایا" جو ہے، کہاں سے چلایا؟ ایسے عام ہاتھ سے چلایا ہے یا کس چیز سے چلایا ہے؟ "عَنِ الْقَوْسِ" سے۔ "عَنْ" بتا رہا ہے کہ وہ جو چلایا گیا، وہ جو دور ہوا، وہ ہوا ہے کمان سے۔ تو "عَنْ" یہ بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ خوب!
بس ایک ہی معنی انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے، اور بھی معنی ہیں لیکن فی الحال کیونکہ پہلی کتاب میں ہم اس کو یہاں پر ذکر کریں گے تو پھر بہت زیادہ درس لمبا ہو جائے گا۔
فِي حرف جر کے معانی
حروف جارہ میں سے ایک اور حرف ہے، وہ ہے "فِي"۔ "فِي" اردو میں حرفی معنی ہوتا ہے "میں"۔ ٹھیک ہے جی؟ اب فرماتے ہیں: یہ "فِي" "میں" کا معنی دیتی ہے۔ "میں" سے مراد یعنی "فِي" آپ کہتے ہیں "لِلظَّرْفِیَّةِ"۔ "فِي" بتاتی ہے کہ جس پر یہ داخل ہوئی ہے، وہ ظرف ہے۔ یعنی کسی کام کا، کسی شے کا وہ محل ہے، وہ جگہ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ مثلاً "سِرْتُ فِي الْبَلَدِ" (میں شہر میں چلا)۔ اب "فِي" بتا رہی ہے کہ یہ جو بندہ چل رہا تھا، کہاں چل رہا تھا؟ اس کے چلنے کی جگہ کیا تھی؟ محل کیا تھا؟ وہ تھا شہر۔ "سِرْتُ فِي السُّوقِ" (میں بازار میں چلا)۔ یہ "فِي" بتا رہا ہے کہ یہ جو "سِرْتُ"، یہ جو چلنے کا عمل میں نے انجام دیا، یہ کہاں دیا ہے؟ اس کا محل کیا تھا؟ وہ بازار تھا۔
فرماتے ہیں: اب مثالیں دے رہے ہیں، جیسے "الْمَالُ فِي الْكِيسِ" (مال تھیلی میں ہے)۔ مال کس میں ہے؟ کیس میں۔ "كِيس" کسے کہتے ہیں؟ یہ تھیلی کو کہتے ہیں۔ اور دوسری مثال دی ہے: "نَظَرْتُ فِي الْكِتَابِ" (میں نے کتاب میں نظر کی)۔ اب ذرا غور کریں۔ یہ "فِي" کیس سے پہلے بھی ہے اور "فِي" کتاب سے پہلے بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ لیکن کیس میں جو "فِي" ظرفیت کا معنی دے رہا ہے، یہ ظرفیت حقیقی ہے۔ کیوں؟ واقعے میں بھی مال اس تھیلی کے اندر تھا۔ مال کا محل وہی کیس، یعنی وہی تھیلی تھی۔ جبکہ "نَظَرْتُ فِي الْكِتَابِ" جو ہم کہہ رہے ہیں کہ میں نے کتاب میں نظر کی، یہاں بھی ظرفیت ہے، لیکن یہ ظرفیت کس کے لیے ہے؟ یہ مجازی ہے۔ اور جیسے تھیلی کے اندر سامان ہوتا ہے، کتاب کے اندر اس طرح نظر نہیں ہوتی۔ تو غور سے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ "فِي" آتا ہے ظرفیت کے لیے، چاہے وہ ظرفیت حقیقی ہو، جیسے "الْمَالُ فِي الْكِيسِ" (مال تھیلی میں ہے)، چاہے وہ ظرفیت مجازی ہو، جیسے "نَظَرْتُ فِي الْكِتَابِ"۔
اسی طرح فرماتے ہیں کہ "فِي" استعلاء کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ یعنی "فِي" کا معنی کبھی کبھی استعلاء، یعنی بلندی کے معنی میں ہوتا ہے۔ یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ "فِي" بمعنی "عَلَى" کے بھی استعمال ہوتی ہے۔ جیسے قرآنِ مجید کی آیت ہے: "وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ"۔ "نَخْل" کہتے ہیں کھجور کو۔ "جُذُوع" ہو گئے ان کے تنے۔ اب یہاں ترجمہ اگر ایک ترجمہ لفظی کریں گے، "فِي" کا معنی "فِي" میں والا کریں گے، تو کیا ہوگا؟ "ہم ضرور تمہیں سولی پر چڑھائیں گے کھجور کے تنوں میں"۔ لیکن جہاں "میں" والا معنی نہیں، جہاں "فِي" بمعنی "عَلَى" کے ہے، یہاں استعلاء یعنی بلندی کے لیئے ۔ "وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ" (اور ہم ضرور تمہیں سولی پر چڑھائیں گے کھجور کے تنوں پر)۔ یعنی جس پر کھجور کے درختوں کے تنے ہیں، ان پر۔ یہاں "فِي" کا معنی "میں" نہیں کرنا، بلکہ "فِي" کا معنی "پر" کرنا ہے۔
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ۔
جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١]، والكاف للتشبيه، نحو: «زيـــد كالأسد»، وقد تكون زائدة، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شيء﴾ [الشورى: ۱۱]، ومذ ومنذ لابتداء الغاية في الزمان الماضي، نحو: «ما رأيته مذ يوم الجمعة أو منذ يوم الجمعة» أي: ابتداء عدم رؤيتي إيّاه كان يوم الجمعة إلى الآن، وقد تكونان بمعنى جميع المدة، نحو: «ما رأيته مذ يومين أو منذ يومين» أي: جميع مدّة انقطاع رؤيتي إيّاه يومان. ورُبَّ للتقليل، ولا يكون مجرورها إلّا نكرة موصوفة، ولا يكون متعلَّقه إلّا فعلاً ماضياً، نحو: «رُبَّ رجل كريم لقيته»، وقد تدخل على الضمير المبهم، ولا يكون تمييزه إلّا نكرة موصوفة، نحو: «ربه رجلاً جواداً لقيته». والواو للقسم، وهي لا تدخل إلّا على الاسم الظاهر لا على المضمر، نحو: «والله لأشربنّ اللبن»، وقد تكون بمعنى رُبَّ، نحو: «وعالم يعمل بعلمه» أي: رُبَّ عالم يعمل بعلمه. والتاء للقسم، وهي لا تدخل إلّا على اسم الله تعالى، نحو: تالله لأضر بنّ زيداً».
اعلم أنّه لا بدّ للقسم من الجواب؛ فإن كان جوابه جملة اسميّة؛ فإن كانت مثبَتة وجب أن تكون مصدّرة بـ«إنّ»
