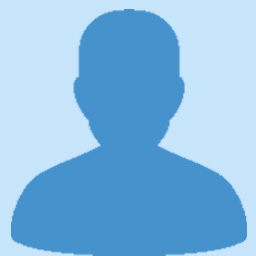کل آغاز یہاں سے کیا تھا کہ یہ علم نَحو ہمیں سکھاتا ہے کہ صحیح عربی کو کیسے لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے حروف ہیں، بہت سارے اسماء ہیں جو عَوَامِل کہلاتے ہیں۔ عَامِل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس پر پہلے آ جائیں، جس پر پہلے عَامِل داخل ہو، وہ کسی نہ کسی حرکت کو تبدیل کرتے ہیں۔ کوئی زَبَر دیتا ہے، کوئی زَیر دیتا ہے۔ ان شاء اللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔
تو انہوں نے کہا تھا: عَوَامِل لَفظِیَّۃ بھی ہوتے ہیں، عَوَامِل مَعنَوِیَّۃ بھی ہوتے ہیں۔ پھر کہا تھا: عَوَامِل لَفظِیَّۃ کچھ سَماعِیَّۃ ہیں اور کچھ قِیاسِیَّۃ ہیں ۔ سَماعِیَّۃ 91 ذکر کیے تھے، اور قِیاسِیَّۃ 7۔ اب جو یہ عَوَامِل سَماعِیَّۃ ہیں، جن کی تعداد 91 تھی، ان 91 عَوَامِل کو علماءِ نَحو نے خاص طور پر یہاں پر علماء عبد القاہر جُرْجَانِی اور اس کی شرح کرنے والے عبد الرحمٰن جامی نے ان 91 کو تیرہ اقسام میں تقسیم کیا ہے، تاکہ بات سمجھنے میں آسان ہو۔
ذہن نشین رہے کہ سارے حروف ایک جیسا عمل نہیں کرتے، سارے اسماء ایک جیسا عمل نہیں کرتے۔ تو انہوں نے اس کو الگ الگ اقسام میں تقسیم کیا ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے اور آسانی ہو۔ مثلاً پہلی نوع انہوں نے تحریر فرمائی ہے حروف کے بارے میں، کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، یا جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ فقط اسم پر داخل ہوتے ہیں، یعنی کسی فعل پر وہ حرف داخل نہیں ہوتے، اور دوسرا پھر جس اسم پر داخل ہوتے ہیں، اس کو وہ جر دیتے ہیں، اس کے آخر میں وہ زَیر بنا دیتے ہیں۔ ان شاءاللہ ہم بتائیں گے کیسے۔
مثلاً یہ حروف ٹوٹل سترہ17 ہیں: بَاء، تَاء، کَاف، لَام، وَاو، مِیم، مِن، إِلَی، عَن، عَلَی، فِي، رُبَّ، مُذ، مُنذُ، حَتَّی، خَلَا، عَدَا۔
اگر آپ نے نحو میر پڑھی ہے تو اس میں یہ شعر تھا:بَاو تَاو کَافُ لَامُ وَاوُ مِیمُ مُذ خَلَا رَبْ حَاشَا۔۔۔
یعنی سترہ حرف ایسے ہیں جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور پھر اس کو جر دیتے ہیں۔ اب اس سے آپ نے دو باتیں سمجھ رہی ہیں:
-
یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، یعنی فقط اسم پر داخل، فعل پر داخل نہیں ہوتے۔
-
یہ فقط اسم پر داخل ہو کر جر دیتے ہیں، یعنی ان کا کام ہے جس پر آ جائیں، اس کو جر دینا۔
جب یہ جر دے لیتے ہیں، ان کا وہ کام ختم ہوتا ہے۔ ہم ان شاءاللہ ان سارے سترہ حروف کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ چونکہ ہر حرف جہاں وہ اسم کو جر دے رہا ہوتا ہے، وہاں وہ ایک خاص معنی بھی دے رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ حروف جو حروف جارہ کہلاتے ہیں، جو اسم کے آخر کو جر دیتے ہیں، یہ جر دینے کے علاوہ کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی اور معنی بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم ان شاءاللہ اس کتاب میں یہ بھی پڑھیں گے کہ ہر حرف جر دینے کے علاوہ ایک اور معنی بھی دیتا ہے، اور ممکن ہے کوئی حرف کئی کئی معنی دیتا ہو۔
مثلاً ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے حروف جارہ میں سے بَاء کو۔ "بِسمِ اللہِ الرَّحمٰنِ الرَّحِیمِ" میں اسم سے پہلے آ گئی بَاء۔ تو اس بَاء نے کہا کہ "بِسمِ اللہِ" میں "مِیم" پر زیر پڑھنی ہے، "بَسمَ اللہِ" نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ چونکہ یہ بَاء جارہ ہے۔
اگر زید سے پہلے بَاء آ جائے، تو "بِزَیْدٍ" پڑھیں گے۔ "بِزَیْداََ " پڑھنا بھی صحیح نہیں، "بِزَیْدُُ" پڑھنا بھی صحیح نہیں ۔ کیوں؟ چونکہ بَاء جار جس اسم پر داخل ہو جاتی ہے، پھر اس کو یہ جر دیتی ہے، اب بِضَرَبَ یہ صحیح نہیں کیوں ؟ کیونکہ یہ حروف جارہ فعل پر داخل نہیں ہوتے ، بِیَضرِبُ بھی صحیح نہیں ۔
حروف جارہ میں سے سب سے پہلے جس کو شروع فرما رہے ہیں، وہ ہے البَاء: بَاء اسم پر داخل ہوتی ہے، ایک اسم کو جر دیتی ہے ۔ دو، اس کے علاوہ یہی بَاء جو یہاں انہوں نے تحریر فرمائے، تقریباً نو(9) معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس بَاء جارہ کے نو معنی ہیں ۔ کہ کہیں پر کوئی معنی دے رہی ہوگی، کہیں پر کوئی اور معنی دے رہی ہوگی، کہیں پر کوئی اور۔ یعنی یہ ہر جگہ بَاء ایک معنی کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہے۔
مثالیں ایک دو دیتے ہیں، تو بالکل واضح ہو جائے گا۔ مثلاً اگر میں کہتا ہوں: "جَلَسْتُ بِالمَسْجِدِ"، اب یہاں بھی بَاء ہے، "المَسْجِدِ" پر داخل ہوئی، اس کو اس نے جر دی: "بِالمَسْجِدِ"۔ اب اس کا معنی ہم کیا کریں گے؟ "میں مسجد میں بیٹھا"۔ اب یہاں اس بَاء نے اردو میں "میں" کا معنی دیا ہے۔
کہیں پر یہی بَاء اور معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے ۔ مثلاً "کَتَبتُ بِالقلِمِ"، اب یہاں یہ بَاء موجود ہے، لیکن "میں" کے معنی میں ہم اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے۔ "میں نے لکھا قلَم کے ساتھ"۔ ہے تو وہی بَاء جو "جَلَسْتُ بِالمَسْجِدِ" میں تھی، لیکن یہاں معنی کوئی اور ہے ۔ یہاں معنی کیا ہے؟ "میں نے لکھا قلَم کے ساتھ"، یعنی قلَم سے مدد لیتے ہوئے میں نے لکھا۔
تو مقصود سمجھانے کا ان کا کیا ہے؟ مقصود ان کا یہ ہے کہ یہ جو حروف جارہ ہیں، جہاں یہ اسم کو جار دیتے ہیں، تو ان کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ سارے حروف جارہ ایک ہی معنی نہیں دیتے، بلکہ جر دینے کے علاوہ ان کے معنی بھی مختلف ہیں۔
بَاء سے کہ بَاء جہاں اسم کو جر دیتی ہے، یہ بَاء تقریباً نو مختلف معنی میں استعمال ہوتی ہے، یا اس کے نو مختلف معنی ہیں۔ اور ہر معنی کی انہوں نے ساتھ مثال بھی دی ہے۔
تیرہ اقسام میں سے پہلی قسم ہے حروف کے بارے میں، کون سے حروف وہ حروف جو اسم کو جر دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف جارہ۔ پہلی قسم آ گئی حروف جارہ کے بارے میں۔
النَوعُ الأَوّلُ : تیرا انواع میں سے پہلی نوع ہے حروف کے بارے میں کون سے حروف ؟ حُرُوفٌ تَجُرُّ الاِسمَ فَقَط وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفًا، جو اسم کو جر دیتے ہیں پہلی نوع آگئی جو اسم کو جر دیتے ہیں ان کو حروف جارہ کہتے ہیں یعنی اسم کو فقط جر دیتے ہیں اور بس اور یہ سترہ حروف ہیں، کل سترہ ہیں۔ ہم ان شاءاللہ ایک ایک کر کے سب کو پڑھیں گے۔