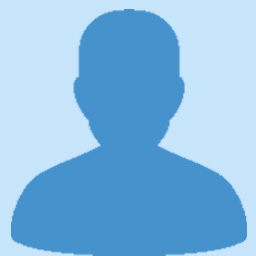شرح مِأَۃُ عَامِل : مِئۃُ کہتے ہیں عربی میں "سو ۱۰۰" کو "عَامِل" کا مَعنی ہوتا ہے، یعنی "عَمَل کرنے والا"۔ ویسے تو "عَامِل" اب آپ ان شاءاللہ عِراق جائیں گے یا جس بھی عربی ملک میں جائیں گے، تو "عَامِل" وہ کہتے ہیں مَزدُور کو، کام کرنے والے کو۔ فلان بندہ کون ہے؟ فلان شَخْص "عَامِل" ہے، یعنی وہ کام کرتا ہے، یعنی "عَامِل" ہوتا ہے۔ مُتَعَلِّم کے مُقابِل میں، فلان "مُتَعَلِّم" ہے، یعنی وہ اسٹوڈنٹ ہے، فلان "عَامِل" ہے، یعنی کام کرتا ہے۔ کوئی بھی کام کرتا ہو۔
یہاں جو ہم بحث شروع کر رہے ہیں، عِلمِ نَحو میں وہ یہ ہے کہ سو عَامِل ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ سو قِسمیں ہیں: اِسم، فِعل، حُرُوف۔ ان شاءاللہ سارے آپ کی خِدمت میں عَرض کریں گے۔ یہ عَامِل ہیں کہ، مثال آپ کو سمجھا دوں، پھر آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جائے گی۔ مثلاً یہ حرف "عَامِل" ہے، یعنی عَامِل ہے تو کیا؟ یعنی جس پر بھی یہ داخل ہوگا، اُس میں کوئی نہ کوئی حرکت کے حوالے سے، اِعراب کے حوالے سے عَمَل کرے گا۔ مثلاً آسان، مثلاً ہم پڑھتے ہیں: "بِسمِ اللہِ الرَّحمٰنِ الرَّحِیمِ"۔ اب ہم نے "بِسمِ اللہِ" یہ جو "مِیم" پر زَیر پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اِس "مِیم" پر زَیر پڑھنے کا جواب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہمیں عِلمِ نَحو بتائے گا۔ کیوں؟ عِلمِ نَحو یہ بتائے گا کہ اِسم سے پہلے آ گئی ہے "بَاء" (بِسمِ اللہِ)، اور "بَاء" جس اِسم سے پہلے بھی آ جاتی ہے، اُس اِسم کے آخر میں زَیر پڑھی جاتی ہے۔ لہٰذا "بِسمِ اللہِ" پڑھیں گے، تو یہ نَحوی قوانین کے مطابق آپ کی دُرست ہوگی۔ اگر "بَسمَ اللہِ" پڑھیں گے، تو وہ غلط ہو جائے گا۔ یہ ہے، یہ ہوتا ہے کہ یہ "بَاء" جو "بِسمِ اللہِ" میں ہے، یہ عَامِل ہے۔
اِسی طرح "بِسمِ اللہِ" میں "اللہ" کی "ہَاء" پر بھی ہم زَیر پڑھ رہے ہیں: "بِسمِ اللہِ الرَّحمٰنِ" پڑھ رہے ہیں، نہ کہ "بِسمِ اللہَ الرَّحمٰنِ" تو نہیں پڑھ رہے ہیں ، "بِسمِ اللہُ الرَّحمٰنِ" بھی نہیں پڑھ رہے تو یہ بھی یہ عِلمِ نَحو ہمیں بتائے گا کہ "بِسمِ اللہِ الرَّحمٰنِ" میں "اللہ" کی "ہَاء" پر زَیر کیوں پڑھنی ہے ۔ یہ عِلمِ نَحو کا کام ہے ۔ کیوں؟ عِلمِ نَحو کہتا ہے کہ اِسم مُضاف ہے لفظ "اللہ" کی طرف، اور جو مُضاف الیہ ہوتا ہے، اُس پر ہمیشہ زَیر (کسرَہ) پڑھا جاتا ہے۔
اب ہم دو چار چیزیں اصل کتاب سے پہلے اِن کو ذہن نشین کر لیں ۔ اردو میں ہم جسے زَبر کہتے ہیں، عربی گرامر میں اُسے "فَتحَہ" کہتے ہیں ۔ ایک زَبر کو "فَتحَہ"، دو زَبر کو "نَصب"، ایک پیش کو "ضَمَّہ"، دو پیش ہوں تو اُس کو عربی میں "رَفعہ" کہتے ہیں۔ ایک زَیر ہوں تو "کسرَہ"، اور دو زَیر ہوں تو اُس کو عربی میں "جَرّ" کہتے ہیں۔ اب آپ نے اِس کو یاد کر لینا ہے، کیونکہ آگے ساری بحثیں پھر اِسی پر ہوں گی۔
بس ، جب ہم کہتے ہیں کہ "بَاء" اِسم کو کسرَہ دے رہی ہے، تو اِس کا مطلب ہے "بَاء" اِسم کو کسرَہ دے رہی ہے، یعنی "بَاء" جس پر داخل ہو گی، اُس پر آخر میں زَیر آ جائے گی۔ تو پہلے یہ نام آپ یاد کر لیں:
-
فَتحَہ: ایک زَبر
-
نَصب: دو زَبر
-
ضَمَّہ: ایک پیش
-
رَفع: دو پیش
-
کسرَہ: ایک زَیر
-
جَرّ: دو زَیر
یہ اچھی طرح آپ کو یاد ہونے چاہئیں، کیونکہ بار بار اِن کا ذکر آئے گا۔ پھر آپ کو پریشان ہوگی: یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔
مِئۃُ عَامِل، سو عَامِل، یعنی سو عَامِل ایسے ہیں: بعض اِن میں سے اِسم ہیں، بعض اِن میں سے حُرُوف ہیں، کہ جو عَمَل کرتے ہیں، کہ جس پر وہ داخل ہوتے ہیں، اُس پر کون سا اِعراب پڑھنا ہے، اُس کو کون سی حرکت دینی ہے، اِس میں یہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان شاءاللہ ہم اِس کو پڑھیں گے۔
اب اِن میں سے کچھ عَوامِل ہیں، اِن کو کہا جاتا ہے "عَوامِلِ لَفظِیَّہ"، اور کچھ کو کہا جاتا ہے "عَوامِلِ مَعنَوِیَّہ"۔
لَفظِیَّہ اُن کو کہتے ہیں جو زبان پر جاری ہو سکیں ۔ مَعنَوِیَّہ اُن کو کہتے ہیں کہ جو زبان پر جاری نہ ہوں، جیسے ہم نے کہا: "بِسمِ اللہِ"، "بَاء" یہ ہماری زبان پر جاری ہوئی، ٹھیک ہے۔
کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زبان پر جاری نہیں ہوتے، اُن کو کہتے ہیں "عَوامِلِ مَعنَوِیَّہ"، وہ ان شاءاللہ آخر میں آئیں گے، کہ یہ کونسے ہیں ۔ مثلاً مُبتَدَا اور خَبَر کی وہاں مثال آئے گی۔
خوب! اب فرماتے ہیں کہ یہ عَوامِل جو لَفظِیَّہ ہیں، جو زبان پر جاری ہو سکتے ہیں، اِن کی پھر دو قسمیں ہیں: ایک کو کہتے ہیں "عَوامِلِ قِیاسِیَّہ"، اور ایک قسم کو کہتے ہیں "عَوامِلِ سَماعِیَّہ"۔ کیا فرق ہے عَوامِلِ قِیاسِیَّہ اور سَماعِیَّہ میں؟ بالکل آسان، آپ جواب دیں گے: سَماعِیَّہ اُن کو کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے اُس لُغت والوں سے، اُس زبان والوں سے سُنا ہے، ویسے اُس کو ہم نے آگے چلانا ہے، کہ وہ کہتے ہیں اِس طرح، ہم بھی کہیں گے اِس طرح ۔ اور قِیاسِیَّہ وہ ہوتے ہیں جو ایک قاعِدہ، قانون اور ضابطے کے تحت ہوتے ہیں، کہ ایک قانون ہوتا ہے، کہ جو لفظ بھی ایسا ہوگا، جو اِس قانون پر پورا آئے گا، وہاں عَامِل ہوگا، اِس کو کہتے ہیں قِیاسِیَّہ ۔ اور جو فقط جیسے ہم نے عرب والوں سے سُنیں، بس اُسی کو لے کے آگے چلتے رہنا ہے، تو اُس کو کہتے ہیں عَوامِلِ سَماعِیَّہ۔ یعنی "سَمْع" کہتے ہیں سُننے کو، یعنی سُنی سُنائی پر چلنا۔ اور "قِیاس" ہوتا ہے کہ نہیں، قواعد اور ضوابط اور قانون کے مطابق چلنا۔
تو یہ عَوامِلِ لَفظِیَّہ، کچھ سَماعِیَّہ ہیں، اور کچھ قِیاسِیَّہ۔ یعنی کچھ کے لیے ہمارے پاس ایک ضابطہ، ایک قانون موجود ہے، جو جو بھی اِس قانون پر پورا آئے گا، ہم کہیں گے یہ عَامِل ہے۔ اور کچھ سَماعِیَّہ ہیں، کہ جیسے ہم نے عرب سے سُنا ہے، بس اُسی کی اتباع کریں گے، کہ ٹھیک ہے جناب، یہ آگے ہیں جو عَوامِلِ سَماعِیَّہ ہیں، کہ جیسے ہم نے عرب سے سُنا، ہم بھی اُن کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ عرب والے اُن کو عَامِل کہتے ہیں، ہم بھی اُن کو عَامِل کہیں گے ، تو اُن کی تعداد ہے 91 (سَماعِیَّہ) اور جو عَوامِلِ قِیاسِیَّہ ہیں، یعنی جن کے لیے ایک ضابطہ اور قاعِدہ کلیہ دیا گیا ہے، وہ ہیں 7۔ 91 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 98۔ اور دو عَامِل ہیں مَعنَوِیَّہ۔ جب دو وہ ساتھ ملائیں گے، تو یہ کتنے ہو جائیں گے؟ پورے سو 100 ٹھیک ہے۔
بس عَوامِلِ سَماعِیَّہ کو تیرہ فصلوں میں اُنہوں نے تقسیم کیا ہے۔ ان شاءاللہ ہم ایک ایک فصل کر کے اُس کو پڑھیں گے، اُس کے بعد پھر ساتھ آ جائیں گے عَوامِلِ قِیاسِیَّہ، اور آخر میں ان شاءاللہ دو آئیں گے مَعنَوِیَّہ ۔ آج پہلا دن ہے، اِتنا میرا خیال ہے دراصل کافی ہے۔